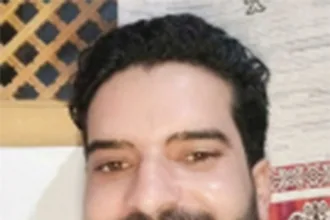فہم وفصاحت
شہباز رشید بہورو
انسانی فہم و فراست کی دنیا میں خیالات کو منظم کر کے ایک نظریہ تشکیل دینے کی صلاحیت کو عبقریت کا استعارہ قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ نظریہ چاہے کسی بھی شعبۂ علم کے متعلق ہو، دراصل علم کے نظم و ضبط اور نظریہ پرداز کی فصاحتِ فہم و بلاغتِ فکر کا ترجمان ہوتا ہے۔ نظریہ علم کے ذخائر میں سے ان قوی و جوہری الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے جو ایک طاقتور برقی لہر کی طرح انسانوں کے علم و عمل کے رخ کو موڑ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ نظریہ پیش کرنے کی تحریک انسانی فطرت میں ودیعت ہے۔ انسان جتنا اس فطری تحریک کو بروئے کار لانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اتنا ہی مؤثر اور نمایاں کردار کا حامل ہوتا ہے۔
یونان کے فلسفیوں سے لے کر مغربی و مشرقی مفکرین تک کی تاریخ میں ان کے معروف اور آج تک یاد رکھے جانے کی وجہ ان کا مال و دولت یا جسمانی ساخت نہیں رہی بلکہ ان کے نظریات رہے ہیں۔ نظریہ پیش کرنے کا ہنر درحقیقت ایک انسان کی تخلیقی صلاحیت کا Litmus Test ہے، جس سے ایک انسان کے تخیلاتی، مشاہداتی و تجرباتی ٹیلنٹ کا اندازہ ہوتا ہے۔ نظریہ علم و عقل کا عطر ہوتا ہے۔ عمیق مطالعہ، گہرا مشاہدہ، وسیع تخیل اور قوی تجزیہ کی صلاحیت ایک مفکر کے نظریے میں منعکس ہوتی ہے۔
نظریات مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے مقاصد کے تعین میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں، اور انسان کو نظریات کی بدولت کچھ کرنے کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ نظریات انسان کو کچھ خاص کرنے کی تحریک فراہم کرتے ہیں، اور نظریات کی یکسانیت افراد کے اندر تنظیمی یا جماعتی وحدت پیدا کرتی ہے۔ نظریات کے بغیر فرد اور ملت بس ایک بے ضابطہ مجموعہ ہوتا ہے، جس کا نتیجہ ہمیشہ تقسیم، تفریق اور ناکامی کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ انفرادی سطح پر ایک آدمی بغیر کسی نظریے کے افراتفری، انتشار اور تضاد کی ناؤ میں بیٹھ کر ہمیشہ زندگی کی پُرآشوب موجوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ اس لیے نظریہ تخلیق کرنے اور اپنانے کے لیے کوشش کرنا بنیادی کام ہے، جسے بروقت انجام دیا جانا چاہئے۔
نظریہ کی اہمیت کے بعد اس کے نفاذ کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اپنی زندگی کے مجموعی رخ کو متعین کرنے کے لیے اپنے آپ کو کسی اچھے نظریے کے سپرد کرنا چاہئے، کیونکہ نظریے کا انتخاب ہی کامیابی اور ناکامی کے درمیان ایک لکیر کھینچتا ہے۔ اگر زندگی بغیر کسی نظریے کے گزاری جائے تو وہ بس لمحات کی سڑک پر ایک ایسی گاڑی کے چلنے مترادف ہے جو بغیر کسی ڈرائیور کے انجانی منزل کی طرف رواں دواں ہو، جسے ہر وقت بھیانک حادثات کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ صحیح اور ٹھوس نظریہ زندگی میں نظم و ضبط کا ایسا نظام قائم کرتا ہے کہ انسان کو اپنی ہر حرکت حد درجہ غایت کا پابند محسوس ہوتی ہے۔ یہ احساسِ پابندی انسان کو انتشار کے بجائے استحکام بخشتا ہے۔
یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر انسان کوئی نظریہ تخلیق نہیں کر سکتا، لیکن کسی نہ کسی نظریے کا پیروکار ضرور بنتا ہے۔ اس لیے صحیح نظریے کے انتخاب کے لیے غور و فکر، مطالعہ، مشاہدہ اور دوسروں کے ساتھ میل جول رکھتے ہوئے ان کی آراء سے استفادہ کرنا اہم ہے۔ ورنہ انسان بعض اوقات کسی ایسے نظریے کا معتقد بن جاتا ہے جو اسے دنیا و آخرت دونوں کے لحاظ سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ میں بہت سے لوگوں نے نہایت غالی نظریات اپنائے جن کی وجہ سے امت میں پھوٹ پڑی اور بعض حضرات نے قومیت کے محدود اور متشدد تصور کو اپنا کر جس راستے کا انتخاب کیا، وہ انہیں صحیح منزل کے برعکس سراب کے گرداب میں پھانسنے کا سبب بنا۔ مثلاً خوارج جنہوں نے سخت گیر نظریہ اپنا کر جو نقصان اپنے آپ کو اور امت کے اتحاد کو پہنچایا، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ان کے نظریات ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننے کے بجائے گمراہی کا سبب بنے۔
اسی طرح مصطفیٰ کمال اتاترک (Mustafa Kemal Atatürk) کی مثال دی جا سکتی ہے، جس نے ترک قوم پرستی کے نظریے کو اسلام کے بنیادی تصورات کے خوبصورت اور معتدل نظام سے جدا کر کے خلافتِ عثمانیہ کا خاتمہ کیا، اور جو نقصان مسلمانوں کو پہنچا، شاید یہ ملت اسے کبھی معاف نہ کرے گی۔
نظریہ چونکہ ایک انسان کی دماغی حالت (State of Mind) کا ترجمان ہوتا ہے، اس لیے وہ دوسرے انسان کی ذہنی کیفیت کو متاثر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس اثر پذیری کی باقاعدہ ایک سائنسی توجیہ بھی موجود ہے، جسے Ideological Contagion کہا جاتا ہے۔ انسانی دماغ میں موجود Mirror Neurons اسی مظہر کی وضاحت کرتے ہیں — یعنی جب ہم کسی کے جذبات، رویّے یا خیالات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمارا دماغ لاشعوری طور پر اُن کی نقل کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ بنیادی میکانزم ہے جس کے ذریعے ایک فرد کے نظریات دوسرے کے ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
بہترین نظریات دوسروں کے دماغ کے اندر یکساں قسم کا Neural Pathway پیدا کر کے Neural Synchrony یعنی دماغی ہم آہنگی کو وجود بخشتے ہیں۔ انسان چونکہ ایک پیچیدہ مخلوق ہے، اس پر اس کے ماحول، تربیت اور تعلیم کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے نظریات کی قبولیت یا عدم قبولیت کا انحصار ایک فرد کے پس منظر پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر ایک فرد کے پس منظر میں مذہب کی تاثیر رہی ہے تو وہ شخص مذہبی نوعیت کے تصورات کی طرف رغبت رکھتا ہوگا۔ اگر کسی کے پس منظر میں انسانی آزادی، عدل و مساوات کا چلن رہا ہوگا تو وہ شخص لبرل تھنکنگ کا حامل ہوگا۔
اسی تناظر میں علامہ اقبال اور جان لاک (John Locke) کی مثالیں نہایت نمایاں ہیں۔ علامہ اقبال ایک مذہبی و روحانی ماحول میں پلے بڑھے، ان کے والد نہایت متقی اور پرہیزگار تھے، اس لیے اتنی اعلیٰ فلسفیانہ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ان کی فکر اسلامی و دینی رہی۔ اس کے برعکس جان لاک سترھویں صدی میں یورپ کے سیاسی انتشار اور انگریزی انقلاب کے دور میں پلے بڑھے، اس لیے ان کے نظریات آزادی، تجربے، عقل، مساوات اور قانون کی بالادستی پر مبنی تھے۔
نظریات عوام الناس کے شعور کو Hijack کرتے ہیں۔ ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے شعور کو Hack کر پاتے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ شعور کو اپنے زیرِ اثر لے لیتے ہیں۔ ہر انسان کی شعوری سطح مختلف ہوتی ہے، اس لیے نظریات کی یہ قوتِ ہیکنگ شعور کی مختلف تہوں کو متاثر کر کے ایک نوعیت کی ذہنی حرکیت یا Mental Dynamism پیدا کرتی ہے، جس کے زیرِ اثر ایک فرد کے رویّے میں تبدیلی کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔
شدت پسند نظریے سے وابستہ شخص میں شدت پسندانہ برتاؤ کی جھلک دیکھی جاتی ہے، جبکہ قومی پرستی کے نظریے سے متاثر شخص میں فخر اور قربانی کا رجحان پایا جاتا ہے، جیسے بھگت سنگھ اور اشفاق اللہ خان۔ اشتراکی نظریے سے وابستہ افراد اپنے نظریے کے نفاذ کے لیے انقلاب کو ضروری سمجھتے ہیں اور اس کے لیے وہ جان کی بازی لگانے سے نہیں کتراتے، جیسے چے گویرا (Che Guevara) جس نے اقوامِ متحدہ میں جا کر ’’قوم یا موت‘‘ کا نعرہ بلند کیا۔ حتیٰ کہ بعض افراد اپنے نظریے کی سربلندی کے لیے جان کی بازی لگانے تک چلے جاتے ہیں۔
نظریہ ایک فرد کی تمام صلاحیتوں کو اپنے نفاذ کے لئے استعمال کرتا ہے۔ نظریہ ایک فرد کی تمام قوتوں کو کھینچ کر اپنی بالیدگی اور اپنے ارتقاء کے لئے استعمال کرتا ہے۔ نظریہ ایک فرد کی تمام صلاحیتوں کو کھینچ کر اپنی بالیدگی اور اپنے ارتقاء کے لئے استعمال کرتا ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظریہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے جواب میں یہ الفاظ شاید کسی حد تک جواب کا حق ادا کر سکتے ہیں کہ نظریہ انسان کی خوشحالی کے ساتھ ساتھ انسان کے لئے سکونِ قلب کا ذریعہ بھی بننا چاہیے۔ اگر کوئی نظریہ انسان کی مادی خوشحالی کے قیام کے لیے تمام تر صفات سے متصف ہو لیکن سکونِ قلب یا تطہیرِ قلب یا تذکیۂ نفس کے لیے کوئی مواد نہیں رکھتا ہو تو ایسا نظریہ اگرچہ نظریہ کی تعریف میں شامل ہوگا، لیکن نظریہ کی کونٹربیوشن کے ضمن میں وہ نقائص کا مینارہ بنتا ہے، جو اگرچہ اپنے وجود کی بلندی سے لوگوں کو متاثر تو کرتا ہے لیکن کسی بھی صورت میں ایک بہترین پناہ گاہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔
جیسے کارل مارکس کا نظریہ بظاہر بہت متاثر کن ہے لیکن گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو انسانیت کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے۔ اس نظریہ کے نفاذ کے لئے کئی لاکھ لوگوں کو جان گنوانی پڑی، لیکن یہ نظریہ انسانیت کے حقیقی مفاد میں ایک دن کے لئے بھی قائم نہ رہ سکا۔ اسی طرح داروین کے نظریے کا جو اثر علوم کے مختلف شعبہ جات پر مرتب ہوا، ہر کوئی حیران ہوتا ہے، لیکن جو حیوانی تعبیر وہ تاریخِ انسانی کو دیتا ہے، اس کے نتیجے میں انسانی تہذیب کی چولیں ہل گئیں۔
[email protected]