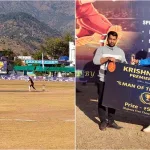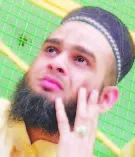ایسے (Essay) جسے اردو میں’ انشائیہ‘ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے مغرب کے ادب کی ایک صنف ہے اور اس صنف کو معرضِ تخلیق میں لانے کا شعوری عمل فرانس کے دانشور مائیکل ڈی مانتین (Michal-De-montaigne)سے منسوب ہے۔مانتین نے اپنی فعال زندگی کے اختتام پر ضعیف العمری کے دور میں اپنے لمحاتِ فراغت کا یہ مصرف نکالا کہ اپنے تجربوں اور مشاہدوں کی روشنی میں مختلف موضوعات پر اپنے غیر مربوط خیالات کو قلم بر داشتہ لکھنا شروع کر دیا ۔مانتین کی یہ عجیب و غریب باتیں چھپ کر سامنے آ ئیں تو اس نے اپنے قارئین کو مخاطب کر کے کہا:میری یہ کتاب دیانت کی امین ہے۔اسے لکھنے کا مقصد ذاتی اور داخلی ہے۔اسے لکھتے ہوئے آ پ کی خدمت یا اپنی شہرت کو ملحوط نہیں رکھاکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں ۔ میرے پیشِ نظر تو دوستوں اور عزیزوں کی مسرت ہے تاکہ جب میں مر جائوں ۔۔اور عنقریب ایسا ہو نے والا ہے تو میرے کر دار اور مزاج کی بازیافت سے مجھے اپنی یادوں میں زند رکھ سکیں ۔‘
مانتین کے تجربوں اور مشاہدوں میں زندگی کی صداقت شامل تھی ،اس کے انکشافِ ذات میں ندرت ِ خیال کا نادر عنصر موجود تھا اور یہ تصنع اور بناوٹ سے پاک تھا۔ بلاشبہ مانتین اپنی کتاب کاموضوع خود تھا لیکن اس نے اپنی ذات میں اپنی عظمت کے نقوش شامل نہیں کئے جب کہ دنیا کے بیشتر مصنفین اپنی ذات کو مرکزِ عالم سمجھتے ہیں اور بقائے دوام کا تاج خود ہی زیبِ سر کر لیتے ہیں لیکن مانتین درویش مزاج انسان تھا۔ہنری آ ف ناروے کے دربار میں اسے ایک اعلیٰ عہدہ پیش کیا گیا تو اس نے قبول نہ کیا۔اس نے زمانے کے تہذیبی مزاج کا پورا ادراک رکھنے کے باوجود فطرت سے ہم آ ہنگی پیدا کی اور گر د و پیش کی چیزوں کی تصویر کشی سادہ طبعی سے کی تو یہ تقاضابھی کیا کہ ’ میری کمزوریوںکا مطالعہ زندگی کے ساتھ کیجئے‘۔مانتین کی یہ معمولی سی بات غیر عمولی بات بن گئی اور اس نے قاری کو نہ صرف اپنی طرف متوجہ کر لیا بلکہ اپنی ذات میں داخل ہونے کے لئے انشائیہ ( ایسّے ) کی کھڑکی بھی کھول دی ۔اور تسلیم کر نا پڑے گا کہ مانتین کا یہ اعلامیہ ایک بے ساختہ،نا تراشیدہ ہلکی پھلکی لیکن بے حد خیال افروز اور بہجت آ فریں صنفِ ادب کا نقطہ آ غاز بھی تھا۔جسے زمانے نے قبول ِ عام کا درجہ دیااور اس کی خوشبو پھیلنے لگی تو انگریزی زبان کے ادیبوں نے اسے اپنے دل میں زیادہ بسایااور بیکن۔ابراہم کائولے۔ایڈیسن۔سٹیل۔ہزلٹ۔جانسن۔گولڈسمتھ۔چارلس لیمب۔ڈیکوئنسی۔سٹیونسن۔چسٹرٹن۔رابرٹ لِنڈ۔جانسن۔پرسٹلے۔وولف۔بیلاک۔بیر بہوم۔اور ایلفا وغیرہ انشائیہ نگار رونما ہو ئے جو اپنی قوم کو اشیاء ،مظاہر او ر مناظر کا بہجت افروز زاویہ دکھانے کی قدرت رکھتے تھے ۔
سر سید احمد خان لندن گئے اور انہوں نے انگریزی رسائل ٹیٹلر اور اسپکٹیٹر میں انشائیے پڑھے تو ایڈیسن اور سٹیل کو اپنی تہذیب کا پیامی شمار کیا اور وطن واپس آ ئے تو ان کی تقلید میں رسالہ ’تہذیب الاخلاق ‘ جاری کیا اور اپنی انشا پر دازی سے وہی کام لینے کی کو شش کی جو ایڈیشن اور سٹیل لے رہے تھے۔ بیسویں صدی کے ثلث سوم میں اردو صحافت کو فروغ حاصل ہوا تو بعض نثر نگاروں کے مضامین میں انشائی خصوصیات بھی رونما ہو نے لگیں اور اس سلسلہ کو بیسویں صدی کے نصف اول میں زیادہ فروغ حاصل ہواچنانچہ ظہیر الدین مدنی ،سید صفی مرتضیٰ ،سید محمد حسنین ،ڈاکٹر آ دم شیخ اور اختر اورینوی نے مزاح نگاروں کے مجموعے کے پیشِ الفاظ لکھے تو ان میں انشائیہ کی جزیات پر بھی بحث کی دلچسپ بات یہ ہے کہ انشائیہ (ایسّے ) مغرب میں کثرت سے لکھا گیا اور متعدد نامور انشائیہ نگاروںکے مجموعے بھی شائع ہوئے جن کے آ غاز میںاس دور کے انگریز نقادوں نے انشائیہ کی بوطیقا (پوئیٹکس) پر بھی بحث کی اور ہر انشائیہ نگار کے فن کے انفرادی نقوش دریافت کر نے کی کاوش بھی کی لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انشائیہ کے فن پر انگریزی میں کوئی مبسوط اور مربوط کتاب نہیں چھپی اور اردو میںجو دیباچے لکھے گئے ہیں وہ بھی انگریزی کتابوں کے پیشِ الفاظ سے استفادہ کا نتیجہ ہیں ،مزید بر آ ں یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ مغرب کے ادبی حلقوں میں انشائیہ کو کبھی متنازع قرار نہیںدیا گیا اور اسے بحث کا موضوع بھی نہیں بنا یا گیا اور نہ ہی انشائیہ کو طنز و مزاح کے ساتھ خلط ملط کیا گیا ہے ۔
اردو ادب میں انشائیہ کے باقاعدہ تعارف سے پہلے طنز و مزاح کی روایت فروغ پا چکی تھی اور یہ المیہ حقیقت نظر اندازنہیں کی جا سکتی کہ شاعر جعفر زٹلّی کوہندوستان کے مغل شہنشاہ نے اس کی طنزیہ شاعر پر ہی پھانسی پر چڑھا دیا تھا۔ مزاح کے چند عناصر امیر خسرو کی پہیلیوں ،کہہ مکر نیوں اور فی البدیہہ دو سطری بیتوں میں موجود ہیں جو نہ صرف اپنے زمانے میں زبان زدِ خاص و عام ہو گئے بلکہ انھیں دوامِ ابد مل گیا اور یہ امیر خسرو کی انفرادیت پر منتج ہو تے ہیں ۔ ایک مثال حسبِ ذیل ہے جس کی تخلیق پنگھٹ پر لڑ کیوں کی فر مائش پر ارتجالاً ہوئی :کھیر پکائی جتن سے،چرخہ دیا جلا،آ یا کتا کھا گیا ،تو بیٹھی ڈھول بجا ۔
اردو میں طنزئی و مزاحیہ ادب کو اودھ پنچ کی اشاعت سے زیادہ فروغ ملا ،تاہم اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ زندگی کی سنگلاخ سنجیدگی میں لطافت و بہجت کا زاویہ ہر دور میں طنز و مزاح نے پیداکیا اور اس کے آ ثار ۱۸۵۷ سے قبل کے بالغ فکر اور بلند نظر شعرا کے ہاں دیکھے جا سکتے ہیں ۔ بالفاظِ دیگر طنز و مزاح کو زندگی میں ایک بنیادی قدر کی حیثیت حاصل تھی انیسویں صدی میں مرزا اسد اللہ خان غالب ؔ کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ انہوںنے اپنی فطری قنوطیت پسندی کے باوجود اپنے خطوط میں تبسم زیرِلب پیدا کر نے کیلئے اردو نثر کو استعمال کیا اور اودھ پنچ جاری ہوا تو اس نے ۱۸۵۷ کی شکستِ عظیم کے اجتماعی ملال کو کم کر نے کے لئے شاعری کے ساتھ نثر کے طنز و مزاح نگاروںکو بھی اہمیت دی اور بقول پنڈت برج نارائن چکبست ؔ ’ ایک ایسے وقت میں جب کہ زندگی میں انقلاب انگیز تبدیلیاں پید ا ہو رہی تھیں فضا کو اعتدال پر لانے کی کوشش کی ۔‘( بحوالہ : اردو ادب میں طنز و مزاح ،از ڈاکٹروزیر آ غا)
سقوطِ دہلی کی شکست گزیدہ فضا میں سر سید کی اہمیت اس لئے زیادہ ہے کہ انہوں نے ایڈیسن اور سٹیل کے خطوط پر قوم کو موجود اشیاء ،مظاہر اور مناظر پر تازہ کار نظر ڈالنے اور مشاہدہ کے شگفتہ زاویے ابھار نے کا انداز عطا کیا۔چنانچہ اردو زبان کے نثری ادب میں ایک نئی صنفِ اظہار کے بیج بکھر نے لگے۔جس کے چند تعارف کاروںکا ذکر اوپر آ چکا ہے ۔ لیکن یہ ظاہر نہیں ہو تا کہ ایک نئی صنفِ ادب کو جو نا موسوم تھی فروغ مل رہا تھا ۔یہ اعزاز ڈاکٹر وزیر آ غا کو حاصل ہے کہ لاہور کے ممتاز جریدہ ’ادبی دنیا ‘ کے پانچویں اور آ خری دور میں وہ مولانا صلاح الدین احمد کے مدیر معاون بنے تو انہوں نے اس ناموسو م صنفِ نثر میں پہلے نصیر آ غا کے قلمی نام سے اور پھر اپنے اصلی نام سے کئی مضامین لکھے جو بعد میں کتاب کی صورت میں ’خیال پارے‘ کے عنوان سے شائع ہو ئے ۔’خیال پارے ‘کا پیش لفظ مولانا صلاح الدین احمد نے لکھا اور اردو ادب میں ایک نئی صنفِ ادب کی افزائش کی نوید دی۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ اس دوران میں دائود رہبر،ممتاز مفتی اورامجد حسین کے چند ایسے مضامین شائع ہو چکے تھے جن میں انشائیہ کے جملہ اوصاف مر تکز تھے ۔ اور اب مضامین کی اتنی تعداد جمع ہو گئی تھی کہ اس نئی صنف کے فن پر بحث کرائی جا سکتی تھی۔انشائیہ پر پہلی بحث ڈاکٹر وزیر آ غا نے رسالہ ’ادبی دنیا ‘ میں استوار کی اور اس میں پروفیسر غلام جیلانی اصغر اور پروفیسر نظیر صدیقی کے علاوہ خود ڈاکٹر وزیر آ غا نے حصہ لیا۔میں ’ادبی دنیا‘ ا س بحث کو جدید انشائیہ کی تحریک کا نقطہ آ غاز تصور کر تا ہوںجسے زیادہ فروغ بعد میں ’اوراق‘اور ’ اردو زبان ‘نے دیا ۔ علی گڑھ سے ڈاکٹر ابنِ فرید نے رسالہ ’ادیب ‘ کا انشائیہ نمبر شائع کیا۔ہندوستان سے جو ادباء انشائیہ میں ممتاز ہو ئے ان میں احمد جمال پاشا،رام لعل نابھوی اور محمد اسد اللہ کو اہمیت حاصل ہے ۔ہندوستان کے متعدد تخلیق کار جب انشائیہ اور خالص طنز و مزاح کو خلط ملط کر رہے تھے تو ان تین اصحاب نے انشائیہ کے حقیقی مزاج کو سمجھااور معمولی موضوعات پر خیر معمولی انشائیے لکھے جو ڈاکٹر وزیر آغا کے وضع کر دہ اس تعریف پر پورے اترتے تھے ۔’انشائیہ اس نثر ی صنف کا نام ہے جس میں انشائیہ نگار اسلوب کی تازی کاری کا مظاہرہ کر تے ہو ئے اشیاء و مظاہر کے مخفی مفاہیم کو کچھ اس طور پر گرفت میں لیتا ہے کہ انسانی شعور اپنے مدار سے ایک قدم باہر آ کر نئے مدار کو وجود میں لانے میں کامیاب ہوجاتا ہے ۔‘
ڈاکٹر وزیر آ غا کی اس تعریف سے اختلاف کے کئی زاویے سامنے آ ئے اور کئی اصحاب نے اپنے زاویہ نظر کے مطابق انشائیہ کی اصطلاح کو اپنی تعریف سے منور کر نے کی کو شش کی ۔وضاحت ِ احوال کے لئے احمد جمال پاشا نے ماہنامہ ’اردو زبان ‘ (سر گودھا)میں ایک مضمون میں یہ خیال ظاہر کیاکہ ’انشائیہ کی اصطلاح کثرتِ تعبیر سے ایک خوابِ پریشاں بن گئی ہے ۔‘تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ انگریزی میں انشائیہ کی تنقید تو انشائیہ کی کتابوں کے دیباچوں تک محدود ہے لیکن اردو ادب میں مشکور حسین یاد،ڈاکٹر سلیم اختر، ڈاکٹر وحید قریشی،ڈاکٹر بشیر سیفی،ڈاکٹر وزیر آغا اور اس ناچیز انور سدید نے کتابیں بھی پیش کیں جو انشائیہ کی تحریک کو فعال بنانے میں کامیاب قرار دی جا سکتی ہیں ۔ تاہم اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ پاکستان میں انشائیہ کی تحریک گھن گرج کے ساتھ پر وان چڑھی لیکن ہندوستان میں اسے وسیع پیمانے پر قبولِ عام حاصل نہ ہو سکا۔اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جدید انشائیہ کو متعارف کرانے والے ڈاکٹر وزیر آغا یہاں طویل عرصہ تک انشائیہ نگاروں کی رہنمائی کر تے رہے اور انہیں رسالہ’ اوراق ‘ میں متعارف کر انے کے علاوہ حزبِ اختلاف کے اعتراضات کا جواب بھی لکھتے رہے ۔انہوں نے انشائیہ نگاروں کے علاوہ انشائیہ کے نقادوں کی ایک بڑی جماعت بھی پیدا کی جن میں مشتاق قمر ،جمیل آذر،غلام جیلانی اصغر ،ڈاکٹر رشید امجد ،سلیم آ غا قزلباش ،حیدر قریشی ،ناصر عباس نیر اور اکبر حمیدی وغیرہ شامل ہیں ۔دوسری طرف ہندوستان میں احمد جمالپاشا اوررام لعل نابھوی اردو انشائیہ کے فعال رکن تھے لیکن زندگی نے ان کا ساتھ نہ دیااور وہ منظرِ حیات سے اٹھ گئے ۔چنانچہ اردو انشائیہ کی نمائندگی کا تمام تر بوجھ محمد اسد اللہ صاحب کے کاندھوں پر آ پڑا۔ان کی ادبی اور سماجی زندگی متعدد مصروفیتوں میں منقسم ہے اور ان کی کامیابیوں کا عمودی اور افقی گراف ظاہر کر تا ہے کہ وہ ہر شعبے سے انصاف کر تے اور اسے پوری توجہ دیتے رہے ہیں۔ انھوںنے طنز و مزاح بھی لکھا لیکن تخلیقی شعبہ میں انشائیہ کو فوقیت دی اور ۱۹۸۱میں انشائیوں کا پہلا مجموعہ ’ بوڑھے کے رول میں ‘شائع کیا۔حال ہی میں دوسرا مجموعہ ’ڈبل رول‘منظرِ عام پر آ یاہے ۔وہ ان مباحث سے بھی شناسا ہیں جو انشائیہ کے موضوع پر پاکستان کے اخبارات و رسائل و کتب میں چھپتے رہے ہیں ۔اور ڈاکٹر مناظر عاشق ہر گانوی کے مطابق : ’ان سب کو اور انشائیہ پر دیگر مضامین کو سامنے رکھ کر محمد اسد اللہ نے اندازہ لگایا کہ اس صنف کے تعین میں الجھائوپیدا ہو گیا ہے اور مباحث ِ ردو قبول کے د رمیان شناختی نشان پر سوال کھڑا کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے خود ’انشائیہ کی روایت ۔مشرق و مغرب کے تناظر میں ‘،کے عنوان سے ایک تحقیقی و تنقیدی کتاب لکھ دی جو اس موضوع پر تازہ ترین وقیع کام ہی نہیں بلکہ ہندوستان ( بھارت) میں چھپنے والی انشائیہ کی تنقید پر پہلی جامع اور فکر انگیز کتاب ہے ۔محمداسد اللہ نے یہ کتاب ڈاکٹر وزیر آ غا مر حوم کے نام انتساب کی ہے جو ان کی نظر میںبر صغیر میں اردو انشائیہ نگاری کی تحریک کے کاروانِ سالار تھے ۔
اس یک موضوعی کتاب کے بیانیہ کو چھ ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔پہلے باب میں انشائیہ کے فن پر مغرب ومشرق کے تناظر میں روشنی ڈالی گئی ہے ۔ انگلستان نے اس صنف کو فرانس سے در آ مد کیا تھا اور اس کے داخلی محاسن اور نقوش مختلف مصنفوں نے انگریزی مزاج کے مطابق ابھارے ۔اور کسی فنی تنازعے کو جنم نہیں دیا۔ اس کے برعکس بیسویں صدی میں وزیر آ غا نے سر سید احمد خان کی متعارف کرائی ہوئی اس صنف کی تعریف وضع کی اور اسے مقبولیت بھی حاصل ہونے لگی تو یہ صنف متنازعہ بنادی گئی ۔ڈاکٹر محمد اسد اللہ کا نئی اصناف کے بارے میں نظر یہ ہے:’ ارتقاپذیراصناف ِادب اپنے دامن میں تخلیقی امکانات کا ایک جہاں چھپائے ہو ئے ہوتی ہیں او ادبی تنقید تو ایک سائے کی مانند تخلیق کی پیروی پر مجبور ہے ۔اس سائے کے قدو قامت کا تعین تخلیق کے وجود پر منحصر ہے ۔‘انہوں نے بکھری ہو ئی صنف انشائیہ کے تخلیقی وجود کو تسلیم کیا لیکن جب تنقیدی سائے کے قد و قامت و ساخت کا سوال پیدا ہوا تو اس صنف کاگرد آ لود مطلع بھی ان کے پیش ِ نظر تھا۔چناچہ انہوں نے لکھا ہے: انشائیہ کے ضمن میںایک اہم بات یہ ہے کہ انشائیہ اردو کی سب سے زیادہ متنازعہ صنفِ ادب ہے ۔۔۔۔اس پر جس قدر مباحث وجود میں آئے اردو انشائیہ کامسئلہ اسی قدر الجھتا گیا۔۔۔۔۔ان مختلف و متنوع آراء کی موجود گی میںتفکر اور تلاش و جستجو کی راہیں کھلی ہوئی ہیں ۔‘
اس باب میں ڈاکٹر صاحب نے انشائیہ کے جن متنازعہ امور پر بحث کی ہے ان میں انشاء کا لفظ ،انشائیہ کی اصطلاح ، انشائیہ کی تعریف ،انشائیہ او ر مضمون میں فرق ،طنزیہ و مزاحیہ مضمون اور انشائیہ میں انکشافِ ذات وغیرہ شامل ہیں ۔ موضوعات کی یہ تفصیل ظاہر کر تی ہے کہ محمد اسد اللہ نے اس باب کو کس وسعت سے بحث کا موضوع بنایا ہے ۔ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش نے جو خود بھی تازہ فکر انشائیہ نگار اور اس صنف کے کشادہ نظر نقاد اور انشائیہ کی تحریک کے فعال رکن ہیں،لکھا ہے :’ ڈاکٹر محمد اسد اللہ نے مندرجہ بالا کتاب(انشائیہ کی روایت ،مشرق و مغرب کے تناظر میں )قلم بند کر کے صنف انشائیہ کے سلسلے میںپھیلائی گئی بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ کر نے کی کوشش کی ہے ۔۔۔اس ضمن میں انہوں نے جملہ نقطہ ہائے نظر کو اپنے تجزیے کی کسوٹی پر پر کھا ہے اور حقائق کو اجاگر کر نے کی سعی کی ہے ۔‘
میں یہاں اس ضمن میں’انشاء ‘کے لفظ پر اٹھائی گئی بحث کا حوالہ دوں گا جس کی معنوی تعبیر کے لئے محمد اسد اللہ نے قرآن مجید میںاس لفظ کے استعمال کا حوالہ دیاہے تو فرہنگ ِآ صفیہ سے بھی استفادہ کیا ہے اور ڈاکٹر وحید قریشی ،ڈاکٹر آ د م شیخ ،شبلی نعمانی،عبدالماجد دریابادی اور مشکور حسین یاد کی توضیحات پر بحث کے بعد اپنا نقطہ نظر ان الفاظ میں پیش کیا ہے ۔
’’لفظ ’انشاء ‘ ۔۔۔کے ساتھ وابستہ تحریر اور اندازِ نگارش کا محدود اور تکنیکی مفہوم فارسی میںموجود تخلیقی ادب کے زیرِ اثر ابتداہی سے وسعت آ شنا ہو کر عبارت آ رائی اورحسنِ بیان کے معنوں میں استعمال ہو نے لگا تھا۔انشاپر دازی اسلوبِ بیان کی ایک مخصوص خوبی شمار کی جاتی رہی ہے۔‘‘
’انشائیہ کافن ‘ کے باب میں انہوں نے ڈاکٹر وزیر آ غا ،مشکور حسین یاد اور ڈاکٹر سلیم احمد کے نظر یات کے علاوہ رابرٹ لِنڈ کاحوالہ بھی دیا ہے اور اختلافی نکات نشان زد کر نے کے بعد اپنا موقف حسبِ ذیل پیش کیا ہے :ایک انشائیہ اور غزل کے ایک شعر میں ہمیں گہری مماثلت محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ دونوں میں فنکار کا وہ شخصی اظہار ہے جس کے توسط سے وہ اپنے دل کی بات اور منفرد احساسات ہم تک پہنچانا چاہتا ہے اوراس کا وہ تپیدہ جذبہاظہار کی سعی میںغنائیت کی سر حدوں کو چھوکر دیگر اصناف سے ممتاز پیرایہ اختیار کر لیتا ہے ۔انشائیہ میں ہمیں اسی منفرد زبان و اسلوب کے نقوش ملتے ہیں۔‘
محمد اسد اللہ نے انشائیے کے مباحث کو الجھانے کے بجائے سلجھانے کی کوشش کی ہے ۔انہوں نے ہر اختلافی نکتے پر اپنے پیش رئووں کے خیالات اقتباس کئے ہیں اور بے جا تنقید سے گریز کرتے ہو ئے دلیل کی اساس پر اپنا نقطہ نظر ابھا را ہے ۔وہ اکثر مقامات پر ڈاکٹر سلیم اختر اور مشکور حسین یاد سے متفق نظر نہیں آ تے اور بعض نکات پر انہوں نے وزیر آ غا سے بھی اختلاف کیا ہے لیکن ان کے اختلاف کا انداز شائستہ اور نکتہ آ رائی شگفتہ ہے ۔وہ تنقید میں تہذیب کے مدار کو قائم رکھتے ہیں ۔ میری ناچیز رائے میں یہ باب اس کتاب کا اہم ترین باب ہے اور محمد اسد اللہ کی تنقیدی نظرکی وسعت کو آ شکار کر تا ہے ۔
کتاب کا دوسرا باب مغرب میں انشائیہ کی روایت کے تاریخی مطالعہ کامظہر ہے ۔انہوں نے مغربی ادب کے قدیم نسخوں میں بکھرے ہوئے انشائیہ کے نقوش تلاش کرنے کے بجائے ہائوسٹن پیٹر،کے قولِ فیصل کو قبول کیا ہے ۔
(بقیہ منگلوار کے شمارے میںملاحظہ فرمائیں)