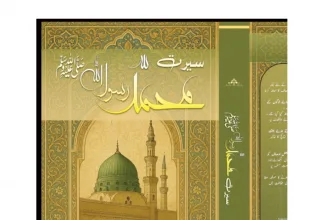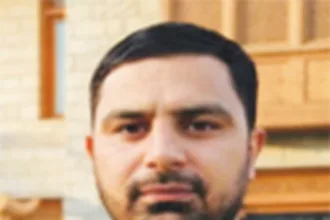شعر : محض ہئیت ہے نہ تکنیک ، صرف تجربہ ہے نہ خیال، بلکہ ماہرانہ لسانی ترتیب و تنظیم کے ساتھ ،فکر و خیال کے تخلیقی اظہار و بیان کا کون سا پہلو تحریر کو شعر بنا دے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا ۔یہی وجہ ہے کہ غزل ہو یا نظم یا کوئی اور شعری صنف کہیں بھی تمام اشعار یکساں معیار اور مزاج کے نہیںہوتے۔میر؎ؔہوںکہ غالب،ؔاقبال ہوں کہ فیض یا آج کا کوئی بھی شاعر ،ہر ایک کے یہاں عمدہ ،اوراعلی اشعار کے ساتھ پست اور بھرتی کے اشعار بھی ملتے ہیں۔ شعر کے اعلی یا ادنی ہونے کا کوئی طے شدہ، اور مستقل گرامر بھی نہیں اس لئے کہ شعر کی کوئی واحد، حتمی اور مستقل تعریف ممکن ہی نہیں ۔ موضوع اور مقصد، عروض اور آہنگ کے علاوہ موزونیت اور غنائیت ، بحر و وزن ، ردیف و قافیہ اور معنی آفرینی اور خیال بندی وغیرہ کو شعر کے شناختی اوصاف قرار دینے سے متعلق علما کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے ۔ اور اس اختلاف رائے کا سبب یہ ہے کہ زمانہ قدیم سے آج تک شعر کی کوئی ایسی تعریف پیش نہیں کی جا سکی جو ہر زمانے میںانسانی فطرت اور اظہار و بیان کے مروجہ فنی و جمالیاتی رویوں کے عین مطابق اور سب کے لئے قابل قبول ہو ۔ اس بات سے انکار نہیں کہ’ شعر‘ انسانی طبیعت اور صنعت کی آمیزش و آویزش کا نتیجہ ہوتا ہے ۔اور ان دونوں چیزوں کی تشکیل و تکمیل ،ردو قبول کے مختلف مرحلوں سے گذرنے کے بعد ہی ہوتی ہے ۔اس لئے ماہرین فن اگر شعر کی مختلف اور متضاد تعریفیں پیش کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ۔ اسی لئے ہر زمانے میں تعریفِ شعر کے حوالے سے علما یہ کہہ کر دامن بچاتے رہے ہیں کہ ’’شاعری چیزے دِگر است ‘‘۔
’شعر ‘‘اصلاًً’’بیان‘‘کے بطن سے پیدا ہونے والی اصطلا ح ہے ۔اور بیان ،انسانی زبان کا وہ جوہر خاص ہے ۔ جو کہنے کو تو ’ محض ’کلام ‘ یا ’بات‘ ہے ،لیکن بات تلخ ہو تو زہر، اور شیریں ہو تو آب حیات ہے۔دل میںاتر جائے تو جادو ہے اور دماغ کو مسخر کر لے تو حکمت ہے ۔بیان کی شعر ی صورت یعنی ’’شعر ‘‘کے بارے میں یہ حدیث مشہور ہے :اِنَ مِنَ الِشعرِحِکمَتہًً وَ اِنَ مِنَ البَیانِ سِحراً ترجمہ :(بے شک بعض اشعار حکمت ہیں اور بعض بیان جادو ہیں)
حضرت علی ؑکایہ قول مبارک بھی’شعر ‘ کی اہمیت اورمعنویت واضح کرتا ہے : اَلشعر ُمِیزانُ القوَلِ و رَواَہُ بعضُہمُ،الشِعرُمیِزانُ القوم، ترجمہ :(شعر قول کا پیمانہ ہے ،یا بقول بعضے ، ’شعر قوم کا پیمانہ ہے .لیکن نہ تو ہر شعر میر ؔ کے اکثر اشعار کی طرح جادو اثر ہوتا ہے اور نہ ہی اقبال کی طرح حکیمانہ ہوتا ہے بلکہ اکثر و بیشتر، شعر میں ذاتی جذبات و کیفیات کا ہی بیان ہوتا ہے جو قاری پر مثبت ،تعمیری اثر ات بھی مرتب کر سکتا ہے اور منفی جذبات و کیفیات پیدا کرنے کا موجب بھی بن سکتا ہے ۔حضرت علی کے اس اشارے کی معنی خیزی کو آج بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کے ’شعر ‘سے محض فرد ہی نہیں ’قوم کی طبیعت اورشعور و لاشعور کا بھی اندازہ ہوتا ہے ۔
اب سوال یہ سامنے آتا ہے کہ پہلے پہل شعر کس نے کہاں کس زبان میںکہا اس کا کوئی سراغ ابھی تک نہیں ملا ہے خود مشرق کی ’’اُم اللسان‘‘ عربی زبان کی ابتدائی شاعری کے بارے میں بھی تحقیق ’’دور جاہلی ‘‘سے آگے نہیں بڑھ سکی ہے۔ویسے کئی عربی اد ب کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ’’عرب میں شاعری کا آغاز مُضَرؔ بِن نزار سے ہوا ۔اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ’ ایک دن وہ اونٹ سے گر پڑا اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ۔درد اتنا تھا کہ وہ، رو رو کر ’واید ہ‘ ،وایداہ ‘ (ہائے میرا ہاتھ ،ہائے میرا ہاتھ )پکارتا رہتا تھا اونٹ پر اس درد بھری آواز کا یہ اثر ہوا کہ وہ مستانہ وار جھومتا ہوا تیز رفتاری سے چلنے لگا ،۔مُضَر کا غلام بھی ہوشیار تھا ،اس نے وایدا،وایدا ،کو’حُدی ‘(شتر بانی کا نغمہ )بنا لیا ۔اس حُدی کے بطن سے ہی شعر کی پیدائش ہوئی اور وقت کے ساتھ اس کا ارتقا ہوتا رہا ، شعرگوئی پھلتی پھولتی رہی ۔یہاں تک کہ مہلہلؔ اور مرقش اکبر کے طفیل شعر گوئی کو ایک مستقل فن کا درجہ دے دیا گیا ۔
لیکن عربی شاعری کے بعض ناقدین اس مفروضے کو بے بنیاد ٹھہراتے ہیں ۔ ڈاکٹر عبد العلیم نے لکھاہے
’’عربی شاعری کے بالکل ابتدائی نمونے سامنے نہیں ہیں۔شعر جاہلی (دور جاہلیت )کا جتنا ذخیرہ محفوظ ہے،وہ زیادہ تر چھٹی صدی عیسوی کی یادگار ہے ،جو مدح،ہجا،،مراثی اور نسیب کے قالب میں ڈھل کر ’’الشعر دیوان العرب ‘‘ کا مصداق بن گیا ہے ۔واقعتاًً ’دور جا ہلیت ‘میںعربوں کے پاس شاعری کے علاوہ اور کوئی ادبی سرمایہ نہ تھا۔ان کی شاعری ان کی قبائلی زندگی کی آئینہ دار تھی‘‘۔
( عربی تنقید کے بنیادی مسائل ؛ص۔۲۹۔)
اس پورے جاہلی دور میں شعر کی کوئی واضح ہئیت نہ تھی۔شاعری کی اکائی شعر نہیں مصرع ہوا کرتا تھا چند مصرعوں کی ایک شعری تخلیق/نظم ہوتی تھی جسے ’اُرجوزہ‘ یا ’ارجوزۃ‘کہتے تھے ۔ اسے ’رجز‘ بھی کہتے ہیں جس کی جمع ’اراجیز‘ ہے اس کے مصرعوں کا وزن ’مستفعلن،مستفعلن،مستفعلن ۔یا مستفعلن مستفعلن ہوتا تھا شائد اسی لئے اس بحر کو ’بحر رجز ‘کہا گیا ہے ۔اردو میں (مرثیہ کے حوالے سے )’رجز ‘کے معنی ’جنگی ترانے کے ہیں ۔لیکن عربی ’رجز ‘یا ’ارجوزہ‘ میں موضوع کی کوئی قید نہ تھی،مدح،ہجو ،فخر،رثا،حسن و عشق(غزل)کسی بھی موضوع کے شعری بیان کی آزادی تھی،چند مصرعے ہم قافیہ بھی ہوتے تھے۔ دوسرے مرحلے میں ’قطعہ کہنے کا رواج عام ہوا ۔ قطعہ میں مصرعہ کے بجائے ’بیت‘ ہوتی ہے۔ وزن کی کوئی قید نہیں رہی دو یا تین ارکان کے بجائے مکمل اوزان میں بھی بیت کہی جاتی تھی ۔ابیات کی تعداد دس یا بارہ سے زیادہ نہ ہوتی لیکن اکثر اشعار ہم قافیہ بھی ہوتے ۔موضوع کی اب بھی کوئی قید نہیں ۔مدح،ہجو ،رثا ،حسن و عشق ،پند و نصاٗئح کسی بھی موضوع پر قطعہ لکھا جا سکتا ہے ۔شعر گوئی کی تیسری منزل میں طویل نظمیںلکھنے کی شروعات ہوئی جنہیں’قصیدہ ‘کا نام دیا گیا اس کی ہئیت وہی تھی جو اردو قصیدے کی ہے۔ قصیدہ میں ،قطعہ سے زیادہ اشعار ہوتے ہیں اور شاعری کا معیار بھی قطعہ سے بہتر ہوتا تھا ۔ عربی قصیدہ ،ہئیتی صنف تھی ،اور اس کے موضوعات مقرر نہیں تھے ۔ جب کہ اردو میںقصیدہ ہئیتی و موضوعی صنف ہے۔ان اسباب کی بناپر بھی شروع میں شعر کی کوئی ٹھوس تعریف سامنے نہیں آ سکی ۔البتہ شعر و شاعر ی سے متعلق بعض شعرا کے ذاتی خیالات کی بنیاد پر بعض عرب محققین اور دانشوروں نے دور جاہلی میں مروج، شعر و شاعری کے معنی ومفہوم اور رسومیات کی نشاندہی کی ہے ۔ لیکن عروج اسلام کے بعد جب عرب جہالت کے اندھیرے سے نکل کر علم و تہذیب کی روشنی میں آئے تو دوسری صدی ہجری کے نصف آخر سے علوم و فنون کی تدوین و ترتیب کے ساتھ ساتھ شعر کے حسن و قبح کی تعئین کا عمل بھی شروع ہوا تو شعر کی تعریف Definition طئے کرنے کی بھی کوششیں کی جانے لگیں ۔عہد اسلام میں جدید کاری( Modernisation ( کا عمل جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا ،دوسرے علوم و فنون کی طرح’’ شعر و شاعری‘‘ کی بھی مختلف النوع تعریفیں پیش کی جانے لگیں ۔الگ الگ ادوار میں شعر کی جو تعریفیں اور وضاحتیں ملتی ہیں انہیں اختصار کے ساتھ ترتیب وار اس طرح سامنے رکھا جا سکتا ہے ۔
۱۔وہ موزوں و مقفی کلام جو،جذبہ و احساس اور حسنِ زبان و بیان کا مجموعہ ہو ،شعر یا اچھا شعر کہلاتا ہے ۔ ۲۔وہ موزوں و مقفی کلام جس میں خیال اور معنی کی ایجاد و اختراع کی خوبیاں بھی ہوں ’شعر ہے۔
۳۔وہ کلام ِموزوں و مقفی ،جس میں افکار و خیالات کی ترتیب اس طرح ہو کہ’ حقیقت‘ ،’وہم‘ اور’ وہم‘ حقیقت‘معلوم ہو ،شعر ہے۔( اردو میں اس کی مثالیں مرزا غالب کے یہاں بھری پڑی ہیں ۔نندلال کول طالب کاشمیری،شمس الرحمن فاروقی ا ور وہاب شرفی کے بعد گوپی چند نارنگ نے بھی اپنی کتاب (’’غالب ؛معنی آفرینی،جدلیاتی وضع ، شونیتا اور شعریات‘‘۱۹۱۳ء) میںغالب کے ایسے اشعار پر تفصیل سے بحث کی ہے۔
۴۔وہ کلام جس میں وزن اور قافیہ ہو یا نہ ہو،خیالی یا اختراعی معانی ہوں، شعر کہلائے گا۔
۵۔وہ کلام موزوں جس میں قافیہ بیشک نہ ہو لیکن جو متداول بحور میں ہو اور ارادتاًًکہا گیا ہو شعر ہے ۔عرب دانشوروں نے شعر کی جو تعریفیں اور توضیحیںپیش کی ہیں ان پر گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے ۔مثلاًً ابوالفَرَج قدامہ بن جعفر (متوفی ۳۳۷ھ) نے اپنی کتاب ’’عقد السحر فی شرحِ نقد ‘‘ میں شعر کی تعریف توضیح کرتے ہوئے کہا ہے’’شعر وہ کلام موزوں و مقفی ہے جو کسی معنی پر دلالت کرے اور بالقصد لکھا جا ئے ‘‘۔قدامہؔ نے ’’بالقصد ‘‘کی شرط اس لئے لگائی کہ ’ ’کلام پاک ‘‘ کلام ربانی ہے ، قصداً کہا گیا کلام نہیں ہے۔ گرچہ قران پاک کی آیات اپنی ساخت کے اعتبار سے نثرمیں ہیں لیکن ان میں شعریت اور غنائیت سے بھرپور مو زوں و مقفی عبارتوں کے بھی بے مثل نمونے موجود ہیں، اور کوشش کے باوجود آج تک ایسی کوئی عبارت نہیںلکھنے میں کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔اسی لئے، انھیں عام معنوں میں شعر نہیں کہا جا سکتا ہے (کفر ہوگا )۔ دوسری بات یہ کہ قرانی آیات کی بنا پر کفار، خود رسول اللہ ﷺ کو ’نئی طرز کا شاعر کہتے تھے ۔ قدامہؔ کا مقصد اس گمراہ کُن مفروضے کی تردید بھی تھا۔ دیکھاجائے تو قدامہ کی تعریف ہی شعر کی اولین مستند تعریف ہے اور عربی ،فارسی اور اردو میںآج تک قدامہ کی یہ تعریف ہی مروج ہے ۔اور دوسرے ناقدین نے اسی کی بنیاد پر اپنے اپنے طور پر شعر کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوششیںکی ہیں ۔ مثلاًً ابن رشیقؔ نے قدامہ سے استفادہ کرتے ہوئے شعر کے بارے میں لکھا ہے۔
’’شعر کی عمارت چار چیزوں سے اٹھتی ہے ،’’لفظ و وزن ،معنی و قافیہ ‘‘۔ اپنے اس نظرئے کی وضاحت کرتے ہوئے ابن رشیق مزید لکھتا ہے ،’’شعر کو مثالاًً’بیت‘ (مکان)سمجھو ۔’فرش‘ اس کا شاعر کی طبیعت ہے اور’ عرش ‘حفظ و روائت (یعنی سابقہ شعرا کے کلام کی آگہی )’دروازہ‘ اس کا مشق و ممارست اور’ ستون‘ اس کے علم و معرفت ہیں ۔ صاحب خانہ معانی ہیں ۔مکان کی شان مکین سے ہوا کرتی ہے ۔وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ۔ اوزان و قوافی قالب و مثال کے مانند ہیں ،یا خیمہ میں چوب و طناب کی جگہ ،جن پر خیمہ تنتاجاتااور کھڑا ہوتا ہے ۔‘ ‘
(مِراۃُالشعر ؛مولوی عبد الرحمن ۔ص۔۴۴۔مجلس ترقی ادب لاہور ۔ ۱۹۰۵ء)
فارسی اور اردو میں شعر و شاعری سے متعلق ، عموماًً عربی روایات و نظریات کی ہی پیروی ہوتی رہی۔لیکن ماحول ،معاشرہاور عصری تقاضوں کے تحت نظریہ شعر میں ترمیم و اضافے بھی کئے گئے ۔ ایک عرصہ تک یہ مانا جاتارہا تھا کہ فارسی میںایران کی آخری درباری زبان ’’پہلوی ‘‘سے قبل ’شعر‘ کا وجود نہیں تھا لیکن عصر حاضر کے مستشرق ثابت کر رہے ہیں کہ قدیم فارسی ،یعنی ’گاتھا‘،اوستا،ژندکی وغیرہ زبانوں میں شعر کے نمونے موجود تھے ۔ اس لئے یہ مفروضہ درست نہیں کہ پہلوی (فارسی )زبان میں ’شعر ‘عرب اور عربی زبان کے اختلاط کے بعد پیدا ہوا۔
رابطہ 9419010472
(بقیہ بدھ کے شمارے میں ملاحظہ فرمائیں)