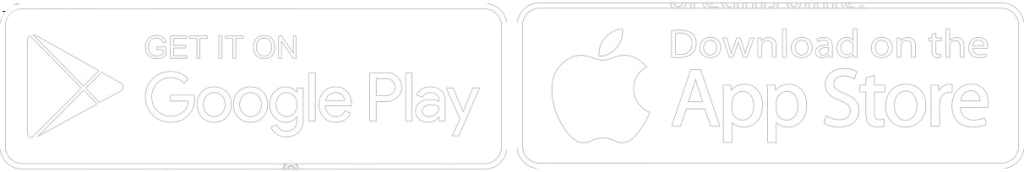خالق کائنات نے انسان کو احساس کی جس نعمت سے نوازا ہے اس کا اظہار انسان مختلف صورتوں میں کرتا ہے۔ عقل و اخلاق کی حسیات انسان کو مخلوقات کے درمیان بے شک ایک منفرد مقام عطا کرتی ہیں، لیکن حس جمالیات انسانی شخصیت کے مختلف دائروں کو حسین و جمیل بنادیتی ہے۔ یہ حس انسانی زندگی میں اس طرح رنگ بکھیر دیتی ہے کہ انسان کی صناعیت اور ظرافت پھیکی پڑجاتی ہے اور نہ پژمردگی کا شکار ہوتی ہے۔ یہی حس عقل کی مجرد دنیا میں کی جانے والی جولانیوں کو پرکشش بنادیتی ہے اور اسی سے اخلاق و عمل کی دنیا میں کی جانے والی سعی و جہد بھی پرکشش بن جاتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اس حس کے زیر اثر وقوع پذیر ہونے والی انسان کی عقلی و عملی کاوشوں نے ایک باضابطہ فلسفے یعنی جمالیات (ایستھٹکس) کو جنم دیا۔ اس فلسفے کو کبھی کبھی فلسفہ ہنر سے تعبیر کیا جاتا ہے جس میں فن پاروں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جبکہ مجرد جمالیات میں ذوق و جمال کی تحسین ہوتی ہے۔ تاہم جمالیات میں اپنی اصل کے اعتبار سے حسن اور ہنر دونوں کا خیال رکھتے ہوئے جمالیاتی تجربات کی تفہیم بھی ہوتی ہے اور اشیاء، اعمال اور فن پاروں کی قدر بھی متعین کی جاتی ہے۔ جمالیات میں اس تحیر اور تلذذ کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے جو فطرت کے حسین نظاروں کو دیکھتے وقت، بصری نوادرات کا مشاہدہ کرتے وقت، موسیقی سے محظوظ ہوتے وقت یا مختلف ادب پاروں سے لطف اندوز ہوتے وقت انسانی دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔
باوم گارٹن نے 1750 ء میں جمالیات کی اصطلاح پہلی بار استعمال کی اور اس سے مراد علم حسیات لی، جس کا بنیادی مقصد حسن کی تلاش قرار دیا۔ تاہم اس سے قبل جمالیات سے مراد وہ علم تھا جو حسن یا جمال اور رفعت کی ہیئت سے متعلق مجرد تصورات پر بحث کرتا تھا۔ اس طرح جمالیات انسانی فکر و عمل اور نطق و بیان کے ساتھ ساتھ مظاہر فطرت میں حسن اور رفعت کو تلاش کرتا ہے اور اس کے ذریعے انسان کے مجموعی احساسات پر رونما ہونے والے تغیر و تبدل یا بالفاظ دیگر انقلاب کا مطالعہ کرتا ہے۔
ظاہر ہے کہ تقریر اور تحریر میں بھی حسن کی تلاش علم جمالیات میں شامل ہے۔ یہی حسن ’’کئی بیانات میں جادو کی تاثیر پیدا کرتا ہے اور کئی اشعار میں حکمت کے موتی بھر دیتا ہے۔‘‘ اسی سے ادب مجموعی طور پر ارفع یا عظیم (Sublime Literature) کا درجہ حاصل کرلیتا ہے۔ تاہم لان جائنس (Longinus) کے مطابق ایسے ادب میں پانچ عناصر (عناصر خمسہ) کا ہونا لازمی ہے۔ ان میں سے پہلے دو عناصر یعنی ’’عظمت خیالات ‘‘اور ’’شدت جذبات‘‘ شاعر یا ادیب کے اندر پیدائشی طور پر موجود ہوتے ہیں یا ہوسکتے ہیں، جبکہ تین عناصر یعنی ’’موزون ترین الفاظ کا انتخاب‘‘، ’’ترکیب الفاظ ‘‘اور ’’صنائع و بدائع کا استعمال‘‘ معاشرے کے ساتھ اس کے تعلق اور اس کی تعلیم و تربیت سے پیدا ہوتے ہیں۔
غالب کی شاعری میں ہمیں ان پانچوں عناصر کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ محققین کے مطابق غالب کا طرز احساس انہیں نہ صرف اپنے عصر کا آئینہ دار بنادیتا ہے بلکہ یہی احساس انہیں عصر سے ماوراء کرتا ہے۔ چونکہ ’’عظمت خیالات ‘‘کا ’’شدت جذبات‘‘ کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لئے ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ ان کی شاہانہ نفسیات نے ان کے اندر نہ صرف الفت ذات یعنی نرگسیت پیدا کی تھی بلکہ اسی سے تعلی کی روایت ان کے ہاں در آئی تھی۔ شخصی، خاندانی اور قومی پریشانیوں اور محرومیوں نے غالب کے فلسفیانہ مزاج کی تشکیل کی اور انہوں نے نفی سے اثبات کا درس لیا۔ فرماتے ہیں۔ ؎
رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہوگئیں
اسی طرح غم کی شدت اور ناگزیریت کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ ؎
غم اگرچہ جانگسل ہے پہ کہاں بچیں کہ دل ہے
غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا
تاہم غالب کی نازک نفسیات پر غم عشق نے بھی اچھے خاصے داغ چھوڑے تھے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ مرزا کی ’’ہائے ہائے‘‘ردیف والی مشہور غزل کسی ترک خانم، جو ان سے اپنے کلام پر اصلاح لیتی تھی، کا مرثیہ ہے۔ اس غزل کے دو اشعار یہاں درج کیے جاتے ہیں۔ ؎
عمر بھر کا تو نے پیمان وفا باندھا تو کیا
عمر کو بھی تو نہیں ہے پائیداری ہائے ہائے
خاک میں ناموس پیمان محبت مل گئی
اٹھ گئی دنیا سے راہ و رسم یاری ہائے ہائے
لیکن زمانے کی ستم ظریفی کے باوجود غالب کی خودبینی، الفت ذات اور انا پسندی اپنی جگہ قائم رہی۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا کبھی اپنے کلام میں تعلی سے باز نہ آئے۔ فرماتے ہیں ۔ ؎
ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے
کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور
اور۔؎
میں چمن میں کیا گیا گویا دبستاں کھل گیا
بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہوگئیں
ظاہر ہے کہ اسی ارفع یا عظیم شاعری میں فلسفے کی باریکیاں، جس میں نوافلاطونیت قابل ذکر ہے، بھی سما سکتی تھیں اور اسی کے ذریعے تصوف کا تصور وجودیت بھی بیان کیا سکتا تھا۔ ان باریک تصورات کا ذکر ہمیں غالب کی شاعری میں جا بجا ملتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ غالب نے اس سلسلے میں اپنا کوئی خاص نقطہ نظر بیان کیا ہے۔ تاہم انہوں نے ایک اصطفائیت پسند عبقری (Eclectic Genius) کے طور پر اس سلسلے میں کئی باریک اور لطیف حقائق کو بیان کیا ہے۔ غالب کے اس مشہور شعر کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہئے، بجائے اس کے کہ اس کے ذریعے ان کی بادہ خواری پر مہر تصدیق ثبت کی جائے۔ ؎
یہ مسائل تصوف یہ ترا بیان غالب
تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا
ویسے غالب نے اپنی اس ’’خطا‘‘کا اس وقت بھی برملا اظہار کیا تھا جب انہیں 1857 کے حادثات جانکاہ کے بعد کرنل برنز نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لئے بلایا تھا۔ حالی کے مطابق جب کرنل برنز نے غالب سے ٹوٹی پھوٹی اردو میں پوچھا کہ ’’کیا وہ مسلمان ہیں؟‘‘، تو غالب نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ’’وہ صرف نصف مسلمان ہیں کیونکہ وہ شراب پیتے ہیں جبکہ حرام گوشت کا استعمال نہیں کرتے۔‘‘
غالب نے زندگی کی بے ثباتی اور فنا کو ضرور بیان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی کے توسط سے ثبات اور بقا کو سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے۔ حیات انسانی کے ان دونوں رخوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ۔ ؎
سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہوگئیں
خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہوگئیں
یعنی ’’زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے‘‘ کے باوجود حیات انسانی اپنی تکمیل کی طرف رواں دواں رہتی ہے۔ اسی لئے زمین روز لا تعداد گل ہائے سرسبد کو اپنے اندر سمیٹ تو لیتی ہے لیکن ساتھ ساتھ نئے خوبصورت چہرے زمین کی رنگینی کا سامان کرتے ہیں۔
لیکن حیات انسانی کے پیچھے کا اصل راز غالب کی لطیف طبیعت کو تحیر میں ضرور ڈال دیتا ہے۔ کسی نامعلوم عربی شاعر کے اس شعر۔؎
کل ما ھو کون وہم او خیال
او عکوس فی المرایا او ظلال
(یعنی جو کچھ بھی کائنات میں ظاہر ہے، شاید وہم اور خیال کے سوا کچھ نہیں۔ یا یہ آئینوں میں عکس ہیں یا پھر سائے ہیں!) میں بیان شدہ حیرت کو ہی غالب نے اپنے اس مشہور شعر کے ذریعے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ ؎
نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا
اگرچہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ پہلے مصرعے میں خدا کی زمان و مکان سے ماورائیت کو زبان دی گئی ہے، لیکن دوسرے مصرعے سے نوافلاطونی اور وجودی نظریہ چھلکتا ہے۔ ایسے عام فہم الفاظ سے ایسے لطیف خیال کا اظہار بلاغت غالب کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔
شاید ان تصورات کا اظہار بھی غالب اپنے اصلی درد و کرب کو آہ و فغاں کی صورت دینے کے لئے کرتے ہیں جو ازل سے اپنی اصل سے جدائی پر ہر متنفس کا مقدر ٹھہری ہے۔ اس لئے وہ اس کو کبھی انفرادی آہ و زاری کا جامہ پہناتے ہیں تو کبھی یہی غم کائناتی (Cosmic) ہجر کے نالوں میں تشکیل ہوکر ایک فلسفہ بن جاتا ہے۔ اسی لئے کبھی کہتے ہیں ۔ ؎
فریاد کی کوئی لے نہیں ہے
نالہ پابند نے نہیں ہے
اور کبھی پورے آفاقی فلسفے کے دریا کو نہیں بلکہ سمندر کو اس شعر کے کوزے میں بند کرتے ہیں۔ ؎
نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا
کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا
یعنی انسانی وجود کا خاکہ (اسکیچ) کسی ماہر فنکار (خالق) کی طرف اشارہ کررہا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ خلق کرنے سے قبل بھی اس کے منصوبے میں انسان کی تخلیق موجود تھی۔ اب اس حقیقت کا اعلان (فریاد) خود انسان کا وجود کررہا ہے جو کاغذ کی طرح لطیف اور شفاف ضرور ہے لیکن اسی کی طرح نازک بھی ہے۔ انسان کا ڈھانچہ (پیرہن) کاغذ کی طرح کمزور ہے کہ ہوا اڑائے تو ختم، پانی ڈبوئے تو تباہ اور حرارت چھوئے تو بھسم ہوجاتا ہے۔ لیکن جس طرح انسان اپنا سارا ہنر و فن اور تفکر و تفہم کا پورا سرمایہ یعنی علم کاغذ کے حوالے ہی کرتا ہے، بالکل اسی طرح خالق کائنات نے پوری کائنات کو انسان کے حوالے کیا ہے! اس طرح کاغذی پیرہن کے اس نازک عنصر خاکی کے اندر وہ جوہر (روح) کارفرما ہے جس کے حوالے ’’اختیار کی اصلی امانت‘‘ کی گئی ہے۔ اسی ’’امانت‘‘ کے بل بوتے پر انسان زمین پر اپنا امتیاز قائم رکھتا ہے اور جب اپنی ذمہ داری نبھاکر واپس لوٹتا ہے تو عیش و نشاط کی نرالی کیفیت زندگی میں سہے پورے رنج و غم کو اسی طرح مٹاتی جس طرح دوا درد کا درماں کرتی ہے۔ بقول غالب۔؎
عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہوجانا
درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہوجانا
رابطہ9858471965
(ای۔میل: [email protected])