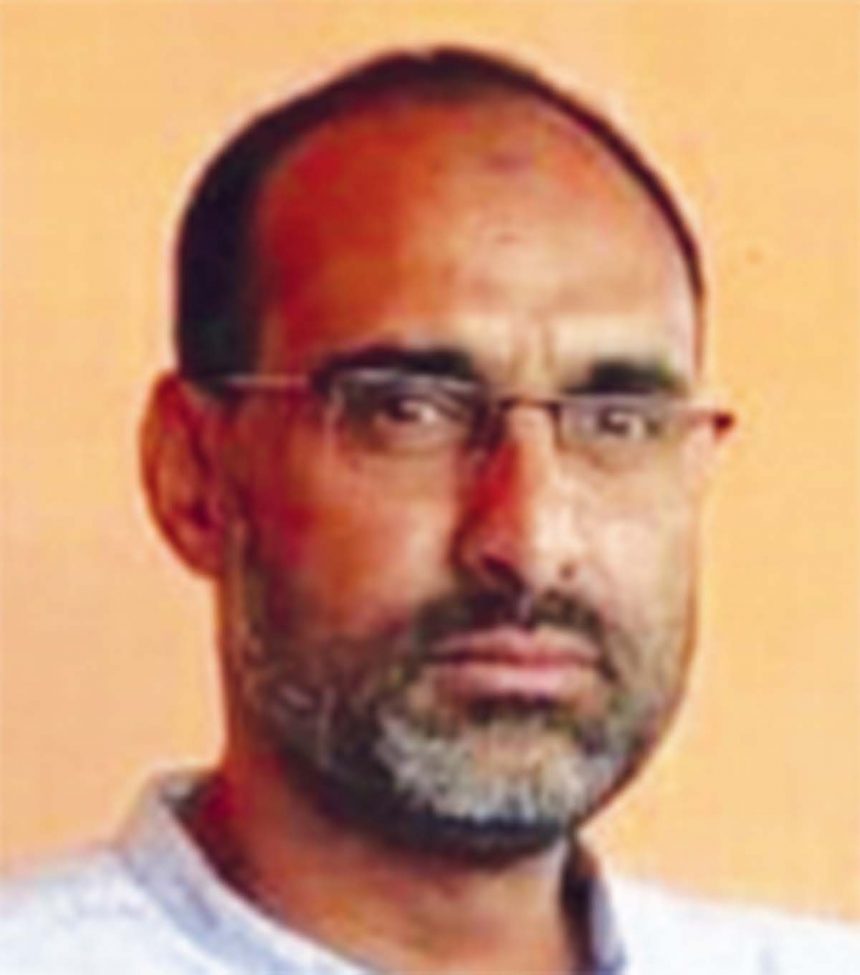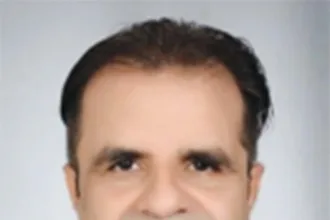معراج زرگر
پچھلےکچھ سالوں سے مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی کے میدان میں انسانی ارتقاء پر ایک گہری چھاپ چھوڑ رہا ہے۔ سائینس کی اب تک کی ترقی میں ٹیکنالوجی انسانی وجود اور کارو بار حیات پر اتنا اثر انداز کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہو رہی ہے۔ میڈیکل سائینس، تعلیم، جنگی ساز و سامان، زمینی وسائل تک رسائی، ہزاروں صنعتوں کی جدید کاری وغیرہ تک اس کا استعمال اگرچہ مفید ہے، مگر کلی طور انسانی عقل و شعور اور انسانی وجود پر اس کے گہرے اثرات کسی المیہ سے کم نہیں۔ دنیا بھر میں ٹیکنالوجی کے ماہرین، فلسفی، اور تِھنک ٹینک مصنوعی ذہانت کے منفی اثرات پر بحث کر رہے ہیں اور انسانی وجود کو لاحق ایک خطرناک چیلینج پر بات کر رہے ہیں۔ اگرچہ وہ چیلینج بہت بڑے ہین اور ان پر بحث کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ میرا موضوع مصنوعی ذہانت کا لکھنے پڑھنے کی حد تک انسانی وجود اور شعور پر اثر کے ضمن میں ہے۔
میرے اپنے محدود زاتی تجربے میں مصنوعی ذہانت کے استعمال اور اس کے نتیجے میں آنے والے انسانوں کی نقلی یا مستعار پہچان ایک لمحہ فکریہ ہے۔ نئی نسل ایک ایسی شعوری فالج یا ذہنی یرقان کا شکار ہوگئے ہیں جس نے انہیں بستر علالت پہ دراز کیا ہوا ہے اور وہ اسی بستر پربہ یک وقت کھانا بھی کھا رہے ہیں اور پیشاب بھی پھیر رہے ہیں۔ شعوری فالج کا ایک ایسا جمگھٹا روز نظر سے گذر رہا ہے جو اپنی اوقات، اپنی علمی استعطاعت، اور اپنے شعوری اور عقلی اٹھان سے ہزاروں گنا زیادہ علمی مضامین مصنوعی تکنیک سے لکھ رہے ہیں اور پھر بحث اور دلیل بھی اسی اوزار سے حاصل کی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور نوائےموز خود ساختہ علمی بونے، اساتذہ اورتحریر و تصنیف اور تحقیق کے میدان کے دیرینہ خد مت گاروں کی مٹی پلید کر رہے ہیں اور پڑھے لکھے طبقے کی ایک کثیر تعداد ان عناصر اور مفلوج وجودوں کی واہ واہ میں لگی ہوئی ہے۔ معاملہ یہاں ہی نہیں رکا ہے۔ بڑے بڑے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں طالبان علم اب سارا مواد چیٹ۔پی۔ٹی۔ یا اسی طرح کی دیگر ٹیکنالوجی سے حاصل کرکے تدریس و تعلیم کا بیڑا بھی غرق کر رہے ہیں۔ معاملہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے۔
پچھلے ہفتے قبلہ احمد جاوید صاحب کی ہائیڈیگر کے 1954میں لکھے گئےمضمون ’’دی کوسچین کنسرننگ ٹیکنالوجی ‘‘پر نشت کو سننے کا موقع ملا اور سنتے ہی رونگٹھے کھڑےہوگئے۔ہائیڈیگر کہتے ہیں کہ ہم عام طور پر ٹیکنالوجی کو آلات یا مشینوں کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت صرف اتنی نہیں ہے۔ یعنی دنیا کو دیکھنے، سمجھنے اور برتنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ ہائیڈیگر نے ٹیکنالوجی کی ماہیت کو ایک خاص اصطلاح میں بیان کیا کہ ہم ٹیکنالوجی کوصرف وسائل کی ماہیت میں دیکھتے ہیں۔ یعنی ٹیکنالوجی انسان کو اس مقام پر لے آتی ہے جہاں وہ ہر چیز دریا، زمین، جانور، حتیٰ کہ انسان کو بھی صرف کام آنے والی چیز کے طور پر دیکھنے لگتا ہے۔ (یہاں گاڑھی اصطلاحات سے گریز کیا گیا ہے)۔
ہائیڈیگر کہتے ہیں کہ جب انسان دنیا کو محض ایک استعمالی چیز کے طور پر دیکھنے لگے تو یہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اس سوچ میں فطرت کی روحانیت، حیرت اور حقیقت کھو جاتی ہے۔ مگر ہائیڈیگر صرف مایوسی نہیں پھیلاتے۔ وہ کہتے ہیں،’’جہاں سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے، وہیں نجات کی سب سے بڑی قوت بھی چھپی ہوتی ہے۔‘‘
احمد جاوید صاحب اس نقطہ نظر کو اسلامی تشکُلات، روحانیت اور فلسفہ کے ہمراہ بیان کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں احمد جاوید صاحب نے عقل، ایمان، اور مصنوعی ذہانت کے باہمی تعلق پر گہرا فلسفیانہ تجزیہ پیش کیا۔ ان کے مطابق مصنوعی ذہانت صرف معلوماتی اور منطقی سطح پر کام کرتی ہے، جبکہ انسان کی اصل قوت اُس کے اخلاقی، روحانی اور جمالیاتی شعور میں ہے۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ اگر عقل ایمان سے کٹ جائے تو وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان کی معنویت کو ختم کر سکتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ٹیکنالوجی کو خدمت گار رکھے، متبادل نہ بننے دے۔احمد جاوید صاحب نے اسلام، فلسفۂ مغرب اور صوفیا کے تناظر میں اس بحث کو پیش کیا کہ کیا عقل مذہب کے خلاف جاتی ہے؟ ان کا مؤقف یہ ہے کہ عقل اگر ایمان یا روحانی شعور کے بغیر علیحدہ ہو جائے، تو وہ اکثر خطرناک اور محدود ہو جاتی ہے۔ مصنوعی ذہانت کے حدود اور صلاحیت پر بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف منطقی، اعداد و شمار پر مبنی کام انجام دیتی ہے۔ اور انسانی شعور، اخلاقیات یا تجزیاتی مشاہدے کی جگہ نہیں لے سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ روحانی تشخیص، حساسات و تجربات، اور اخلاقی موقف مصنوعی ذہانت کے دائرے سے باہر ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ انسان ایک مشین نہیں بلکہ ایک روحانی، فکری اور اخلاقی وجود ہے، اس لئے انسان کو اس کی تابعیت میں نہیں بلکہ اسے قدری نظام میں رکھا جانا چاہیے۔ آخری نتیجے کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ اگر عقل دین کے ساتھ مربوط ہو تو مصنوعی ذہانت ایک موثر خدمت گذار بن سکتی ہے۔ اور اگر عقل ایمان سے الگ ہوجائے، تو مصنوعی ذہانت معنوی اور اخلاقی معنویت سے انسان کو محروم کر سکتی ہے۔
آئیے مسئلے یا معاملے کو ایک نئی جہت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔2008 میں، دی اٹلانٹک نے ایک متنازع سرخی کے ساتھ کور اسٹوری شائع کی، ’’کیا گوگل ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے؟‘‘ اس لمبے مضمون کے امریکی مصنف نکولس کارتھے۔ اس مضمون کو بعد میں ایک کتابی شکل بھی دی گئی۔ کینیسا اسٹیٹ یونیورسٹی امریکہ کے مشہورانفارمیشن سسٹمز کے پروفیسر آرون فرنچ، جو ایک تھاٹ لیڈر، فیوچرسٹ، انوویشن تھیورِسٹ اور پروفیشنل اسپیکر بھی ہیں، وہ نکولس کار کے قول ’’کیا گوگل ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے؟‘‘ کے ضمن میں یہی سوال ایک دوسرے طریقے سے کر رہے ہیں کہ ’’کیا چیٹ جی پی ٹی ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے۔‘‘ اس کا جواب وہ ’’ہاں‘‘ دے رہے ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ سرچ انجن جیسے ٹیکنالوجی ٹولز امریکیوں کی گہرائی سے سوچنے اور علم کو یاد رکھنے کی صلاحیت کو کمزور کر رہے ہیں۔ نکولس کار کی پریشانی کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ لوگ اب حقائق کو یاد رکھنے یا سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ وہ انہیں فوراً آن لائن تلاش کر سکتے ہیں۔ اگرچہ اس میں کچھ سچائی ہو سکتی ہے، مگر سرچ انجنز پھر بھی صارف سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ نتائج کو سمجھیں، تنقید کریں اور سیاق و سباق میں پرکھیں۔
پروفیسر آرون فرینچ مزید کہتے ہیں کہ جنریٹیو اے آئی، جیسے چیٹ جی پی ٹی کے عروج کے ساتھ، انٹرنیٹ صارفین اب محض اپنی یادداشت نہیں بلکہ اپنی سوچنے کی صلاحیت بھی دوسرے کے سپرد کر سکتے ہیں۔ جنریٹیو اے آئی محض معلومات بازیافت نہیں کرتی، بلکہ وہ انہیں تخلیق، تجزیہ اور خلاصہ بھی کرتی ہے۔ یہ ایک بنیادی تبدیلی کی نمائندگی کرتی ہے۔ شاید یہ پہلی ٹیکنالوجی ہے جو ’انسانی سوچ اور تخلیقی صلاحیت‘ کا متبادل بن سکتی ہے۔ وہ فکر مند ہیں کہ لکھنے اور تحقیق کے مصنوعی ٹولز صرف ہماری یادداشت کا سہارا نہیں بن رہے، بلکہ ہماری ’’سوچنے کی صلاحیت‘‘ کو بھی آہستہ آہستہ بدل رہے ہیں۔ ان کا خدشہ ہے کہ اے۔ آئی کے ذریعے معلومات حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے اور اب ہمیں مختلف ذرائع کا موازنہ کرنے، ابہام سے نمٹنے یا تفصیل سے سوچنے کی ضرورت کم محسوس ہوتی ہے اور نتیجے کو طور پر ہماری تنقیدی سوچ میں کمی، تجسس میں کمی، دماغی سستی اور انحصار اور علمی ترقی میں سستی واقع ہوگی۔
پروفیسر آرون فرنچ اپنے مضمون میں ایک نفسیاتی خلل جسے ’ڈ نِنگ۔ کُروگرایفیکٹ‘کہتے ہیں۔ یہ نفسیاتی تھیوری سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ جو لوگ ’’کم علم یا تجربہ‘‘ رکھتے ہیں، انہیں ’اپنی جہالت‘ کا اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ ’زیادہ پُراعتماد‘ ہوتے ہیں۔ جبکہ جو لوگ ’زیادہ علم‘ رکھتے ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی بھی بہت کچھ نہیں جانتے،وہ نسبتاً ’’کم پُراعتماد‘‘ ہوتے ہیں۔ اسی بات کا حوالہ دیکرپروفیسرآرون فرنچ کہتے ہیں کہ یہ فینامینن ایک ایسا نفسیاتی مظہر ہے جس میں کم علم لوگ اپنے سطحی علم پر زیادہ اعتماد رکھتے ہیں۔ کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنا کم علم جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مصنوعی زہانت کی وجہ سے اب اس نفسیاتی خلل میں اضافہ ہوگا۔ کیونکہ ایسے لوگ مصنوعی ذہانت سے حاصل کردہ معلومات کو دُہرا کر سمجھتے ہیں کہ وہ موضوع کو سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ محض سطحی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں، مصنوعی ذہانت کسی کی’ ذہانت کا جھوٹا‘ تاثر پیدا کر سکتی ہے جبکہ اصل میں اس کی علمی محنت کم ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ایک اور فینامینن ’’ماونٹ اسٹیوپڈ‘‘ کی چوٹی پر پھنسے رہتے ہیں۔ یعنی ان کا علم کم اور اعتماد بہت ذیادہ ہوتا ہے۔
’’ماونٹ اسٹیوپڈ ‘‘ ایک ایسا دماغی خلل ہے جو ایک نئے نئے سیکھنے یا لکھنے والے کو ایک ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے جہاں وہ خود کو بڑا ماہر سمجھنے لگتا ہے۔ اس خلل کو ’’حماقت کی چوٹی یا ماونٹ اسٹیوپڈ‘‘ کہتے ہیں۔ پھر جب ایسا شخص دھیرے دھیرے کچھ سیکھنے لگتا ہے تو اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ پھر وہ ایک مایوسی اور وہم کی وادی میں آتا ہے۔ وقت کے ساتھ اگر وہ سیکھتا رہے، تو آہستہ آہستہ اصل مہارت حاصل کرتا ہے۔ پھر اس حالت کو ’’وادی بصیرت‘‘ یا علم کی اصل سطح کہتے ہیں۔
ادب اور تعلیم وہ ستون ہیں جن پر انسانی شعور کی عمارت کھڑی رہتی ہے۔ مگر عصرِ حاضر میں ان دونوں بنیادوں کو ایک عجیب طرح کی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ یہ بیماری مصنوعی ذہانت پر اندھا انحصار اور سطحی ذہنی تن آسانی ہے۔ آج کل کے نوجوان قلم کار جو خود کو شاعر اور ادیب کہلوانے پر بضد ہیں، دراصل اپنی ذات اور تخلیقی وجود کو دھوکا دے رہے ہیں۔ انہیں نہ زبان پر عبور ہے نہ اظہار کے اصول کا شعور، مگر سوشل میڈیا اور اخباروں کے غیر تربیت یافتہ مدیران کی خوشامدی فضا نے انہیں یہ باور کرا دیا ہے کہ وہ بڑے ادیب ہیں۔ جتنا کم علم اور کم فہم ہیں اتنا ہی زیادہ ’خود کو نابغہ‘ سمجھتے ہیں۔ یہ قلم کار سطحی علم اور جذبات کو شاعری اور نثر کا لبادہ پہنا کر ادب کی فضاؤں کو آلودہ کر رہے ہیں۔
ادب کی بگڑتی صورتِ حال میں سب سے بڑا کردار ان مدیران کا بھی ہے جو بغیر چھان پھٹک ہر طرح کا لکھا ہوا کچرا چھاپ دیتے ہیں۔ انہیں نہ معیار کی پرواہ ہے اور نہ قاری کی ذہنی بالیدگی کی۔ یوں رسائل اور اخبارات ’ادبی بازار‘ بن چکے ہیں جہاں ہر کھوٹا سکہ چل جاتا ہے۔ مدیران کا یہ رویہ صرف ادب کا مذاق نہیں بلکہ قاری کے شعور کی توہین بھی ہے۔ اصل اہلِ قلم پسِ پشت دھکیل دیے جاتے ہیں اور جعلی ادیبوں کی بھیڑ غالب آ جاتی ہے۔
کالجوں اور یونیورسٹیوں کی صورتِ حال بھی کچھ مختلف نہیں۔ یہاں نہ صرف طلبہ بلکہ اساتذہ اور تعلیمی ماہرین اپنے مضامین، مقالے اور دیکر تحقیقی مواد تک مصنوعی ذہانت سے حاصل کر رہے ہیں۔ اساتذہ بھی تدریسی مواد تیار کرنے کے لئے مصنوعی ذہانت کا سہارا لیکر تعلیمی محنت اور فکری ریاضت کو خیر باد کہہ رہے ہیں۔ اس خطرناک ترین روش کا نتیجہ یہ ہورہا ہے کہ تحقیق کا معیار گر رہا ہے، تنقیدی سوچ اور تجزیاتی صلاحیت معدوم ہورہی ہے اور طلبا کا ذہن ایک مشینی انجن کی مانند محض معلومات کے ذخیرہ تک محدود ہوگیا ہے۔
ادب کا مقصد انسان کو حساس بنانا اور شعور کو بیدار کرنا ہے اور تعلیم کا مقصد انسان کو تنقیدی اور تخلیقی سطح پرمظبوط بنانا ہے۔ لیکن جب ادیب و شاعر اپنی نااہلی اور کم علمی چھپانے کے لئے مصنوعی ذہانت کا استعمال کریں، مدیران شعور بگاڑنے والا مواد شائع کریں اور جب تعلیم سے وابستہ اساتذہ اور طلاب اپنی ذہنی استطاعت کو ترک کرکے مشین کے پچاری بن جائیں تو پھر ادب اور تعلیم، دونوں کا جنازہ نکلنا لازم ہے۔ یہ وقت سخت خود احتسابی کا ہے۔ ادب کو جعلی تخلیق کاروں اور جاہل مدیران کے قبضے سے آزاد کرنا ہوگا اور تعلیم کو مصنوعی ذہانت کے سہل پسند جال سے نکال کر حقیقی تحقیق، تنقید اور مطالعے کے راستے پر واپس لانا ہوگا۔ ورنہ آنے والی نسلیں ایسے ادب اور ایسی تعلیم کی وارث ہوں گی جو نہ انسان کو انسان رہنے دے گی اور نہ معاشرے کو زندہ معاشرہ بنائے گی۔