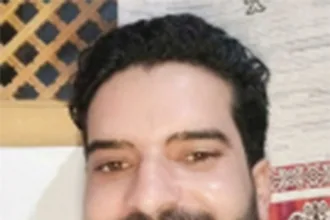اپنی جڑوں سے مضبوط ، معاشرہ ، ثقافت اور شعریات کے اندر پروان چڑھنے والی زبان کی شاعری بھی اتنی زندہ زرخیز اور پُر امکان ہوتی ہے ۔کہ خواہ کسی بھی معاشرہ اور ثقافت میں کیوں نہ چلی جائے جذب و انجذاب اور تغیر و تبدل کے مراحل سے گذرتے ہوئے مقامی معاشرہ اور ثقافت میں بھی جدت طراز یوں کے گُل بوٹے کھلاتی ہی رہتی ہے ۔ کشمیر میں فارسی شاعری کے آغاز و ارتقا اور مزاج و معیار کا مطالعہ فارسی شاعری کی اس غیر معمولی قوت کے حوالے سے ہی کیا جا سکتا ہے ۔
ہم گریرسن کے اس قول سے کہ ’’ برعظیم کی تمام جدید زبانیں اپ بھرنش ہی کے بچے ہیں‘‘ ۔ انکار نہیں کرتے۔ لیکن اس حقیقت سے بھی انکارنہیں کیا جا سکتا کہ ان میں سے اکثر بچوں کو لسانی ، صنفی ، شعری اور فکری ا عتبار سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے ، چلنے اور دوڑنے کا حوصلہ فارسی زبان اور شاعری نے ہی بخشا ہے۔ کہیں براہ راست اپنی گود میں لے کر تو کہیں سبک ہندی کے توسط سے خاص طور پروہ شے جسے لسانی و شعری تہذیب Culturolgy کہتے ہیں اور جس کے عناصر ترکیبی میں لطافت و نزاکت ، فصاحت و بلاغت اور سوز و گذار وغیرہ صفات شامل ہیں، برصغیر کی اکثر جدید زبانوں کو فارسی زبان اور شاعری ہی کی دین ہے ۔ کمال یہ ہے کہ فارسی زبان اور شاعری نے یہ کارنامہ ہر جگہ معاشرتی اور ثقافتی تشخص کا احترام کرتے ہوئے انجام دیا ہے ۔ ہاںمقامی رنگ پر اسلامی رنگ کا غالب آجانا بھی ایک سچائی ہے۔ لیکن اس کی داستان طویل ہے ویسے تاریخ کے حوالے سے اتنی بات تو سبھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہند آمد سے قبل ہی اپنی شاندار تاریخ کے ساتھ فارسی زبان اور شاعری،بعض تحفظات اور مستثنیات کے باوجود اسلامی ثقافت اور شعریات کے اثر و نفوذ سے سر شار ہو چکی تھی بلکہ تقلیب و تطہیر کے مرحلوں سے گزر کر اپنی شعریات کو اس سانچے میں ڈھال چکی تھی جسے’’ اسلامی شعریات‘‘ کہتے ہیں ۔ ہاں ہندوستان کی بت پرست معاشرت ثقافت اور شعریات پر فارسی زبان اور شاعری کے حوالے سے ، اسلامی رنگ کیسے غالب آتا گیا یہ مطالعے کا ایک الگ موضوع ہے ۔ پھر بھی مختصر اً چند تاریخی نکات ازسر نو روشن کرتے چلیں تو مضائقہ نہ ہو گا ۔ کیونکہ ان نکات کا تعلق بہر حال کشمیر میں فارسی زبان اور شاعری کے آغاز و ارتقا اور شاہ ہمدانؒ کی شاعری کے مزاج و معیار سے بھی ہے مثلاً ۷۱۲ء میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ و ملتان اور پنجاب سے لے کر ۱۰۰۱ء میں محمود غزنوی کے حملوں اور پھر ۱۰۳۰ء تک سندھ ملتان اور پنجاب سے لے کر شمال میں میرٹھ دہلی اور نواح دہلی کے علاقوں پر محمودغزنوی ادرّال محمود کے تسلط اور پھر بابر کی فتح ہند تک کا زمانہ تقریباً ۵۰۰ سال کو محیط ہے ۔ اس عرصہ میں شمالی ہندوستان کے ایک بڑے علاقہ پر اسلامی معاشرت اور ثقافت کے ساتھ ساتھ فارسی زبان اور شاعری کا غلبہ قائم ہو چکا تھا۔ اسی دوران امیر کبیر سید علی شاہ ہمدانی المعروف شاہ ہمدان کی پیدائش ۱۳۱۲ء سے دوسال قبل ۱۳۱۰ء مین سلطان علاوالدین خلجی کا لشکر جرار دکن اور مالوہ کے خشک و ترکوزیر وزبر کرتا ہوا کم و بیش پورے جنوبی ہندوستان پر نہ صرف قابض ہو چکا تھا بلکہ بنیادی طور پر فارسی کے ہی توسط سے یہ پورا علاقہ اسلامی معاشرت اور ثقافت اور شعریات کے نُور سے منور بھی ہوتا چلا جاتا ہے ۔ اس عرصہ میں شمالی و جنوبی ہند کے دوسرے علاقوں کی طرح وادی کشمیر میں بھی اسلام کی روح پر ور ہوائیں چلنے لگی تھیں شاہ ہمدان کی کشمیر آمد سے چند سال قبل ہی ترکستان کے سید زادے ، شیخ شہاب الدین سہردردی کے شاگرد حضرت بلبل شاہ کے ہاتھوں رینچن شاہ کے مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد کشمیر میں نہ صرف مسلم حکومت قائم ہوتی ہے بلکہ معاشرتی ، ثقافتی اور لسانی نظام میں بھی اسلامی عناصر کا غلبہ دن بہ دن بڑھتا جاتا ہے ۔ خاص طور پر نظم و نسق میں مسلمانوں کی شمولیت او رکار دربار اور بازار میں سنسکرت کے ساتھ ساتھ فارسی زبان کی حصہ داری سے ہر سطح پر اسلام کے برکات و فیوض کے عام ہونے کی شروعات ہوتی ہے ۔ چنانچہ بقول منور مسعودی ۱۳۴۰ء میں شہمیری دور کے سلطان شہاب الدین کے عہد حکومت میں جب پہلی بار کشمیر میں سید امیر کبیر کا ورود مسعود ہوتا ہے تو ا س وقت تک اسلام ، اسلامی معاشرت ، ثقافت اور فارسی زبان و شاعری کے لیے اس ایران صغیر وادی کشمیر کی زمین ہموار ہو چکی تھی ۔ گریرسن کے ’’ دی امپیریل گریٹیر آف انڈیا ‘‘ اور ڈاکٹر تارا چند کے ’’تمدن ہند پر اسلامی اثرات‘‘ سے لے کر جمیل جالبی کی’ تاریخ ادب اُردو ‘‘ تک متعدد تصنیفات میں بار بار کہا گیا ہے کہ چودھویں صدی کے وسط تک آکر جبکہ امیر کبیر شاہ ہمدان کی کشمیر آمد ہوئی تو براعظم کے ایک بڑے علاقے میں فارسی زبان طبقہ شرفا کی کم وبیش لنگوا فرینکا بن چکی تھی اور دوسرے طبقوں کی زبانیں اور بولیاں بھی فارسی کے لسانی نظام کے قریب آنے لگی تھیں اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ سندھ ، پنجاب ، ملتان ، دکن ، گجرات ، راجپوتانہ ، مہاراشٹر اور دلی ِ سے لے کر کشمیر تک بنیادی طور پر فارسی اور فارسی سے متاثر زبانوں ہی کے توسط سے اسلامی معاشرت اور ثقافت کا آفتاب تازہ بڑے کرو فر سے اُجالے بکھیرتا رہتا ہے ۔ اس اعتبار سے برعظیم میں فارسی اور فارسی سے متاثر زبان اور شاعری کے آغاز و ارتقا کی داستان اس خطہ میں دین اسلام کی توسیع و اشاعت کی بھی داستان ہے اور شاہ ہمدان اس داستان کا روشن ترین باب ہیں یوں تو شاہ ہمدان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں لیکن بنیادی طور پر وہ داعی اسلام تھے اور ان کی شعری و نثری سرگرمیوں کی غرض و غایت بھی دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہی ہے ۔ پروفیسر غلام رسول ملک نے ’’ چہل اسرار ۔ غزلیات شاہ ہمدان ‘‘ مرتبہ پروفیسرمنور مسعودی کے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ :
’’۔۔۔نظم و نثر میں ان کی کلک ِ گو ہر بار سے جو کچھ صادر ہوا ہے وہ بھی ان کی داعیانہ حیثیت کا ایک پرتو ہے اور اسکی مناسب تفہیم اور تعئین قدر کے لیے اس بات کا ذہین نشین رہنا بہت ضروری ہے بالفاظ دیگر انکی شاعری تبلیغی یاد ینی شاعری ہے اور اسے اسی حیثیت سے پرکھا جانا چاہے‘‘۔
شاہ ہمدان کی شاعری ۔ بحیثیت مجموعی دینی اور تبلیغی شاعری ہے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے ۔ لیکن شاہ ہمدان کی شاعری ، اگر فارسی شاعری ، خصوصاً ’’فارسی غزل‘‘ کی شعریات کے حوالے سے بطور ،شاعری پڑھی اور قبول کی جائے تو معلوم ہو گا کہ شاہ ہمدان کی شاعری صرف اور محض اس وجہ سے بڑی شاعری نہیں ہے کہ اس کا سرچشمہ دین اور مقصد تبلیغ ہے ۔ بلکہ اس وجہ سے بھی بڑی شاعری ہے کہ شاہ ہمدان نے اپنی غزلوں میں لسانی و شعری اور فنی و جمالیاتی مضمرات کو اس غیر معمولی شاعرانہ مہارت کے ساتھ برتا ہے جو مہارت کسی بھی شاعری کو بڑی شاعری بناتی ہے ۔ اس کا اندازہ شاہ ہمدان کے درج ذیل اشعار سے لگایا جا سکتا ہے ۔
گر ہمامی قاف قربی بال ہمت برکُشا
در فضائی لامکان با قدسیاں انبار شو
( غزل ۵۔ شعر ۸۔ اگرتم کوہ قاف کے عنقاہو تو ہمت کے پر کھول دو اور لامکان کی فضاؤں میں پرواز کر کے فرشتوں کے ہمراہی بن جاؤ۔
چودر دریائے وحدت گُم نہ گشتی
ازانت درُ عرفاں در شکم نیست
غزل ۴۔ شعر ۔۷۔ چونکہ تم نے دریائے و حدت کی غواصّی نہیں کی ہے اس لیے تمہارے وجود کے اندر عرفان و ادراک کے موتی نہیں ہیں۔
گرآتش فراقش با صبر یار بودی
اندوہ اشتیاقش در دیدہ خار بودی
غزل ۔ ۶۔ شعر ۔۱۔ اے کاش کہ معشوق سے جدائی کی آگ کے ساتھ ساتھ دیدار یار کے لیے صبر کی طاقت بھی ملی ہوتی اور شوق دیدار کا کرب آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا رہتا ۔
یوں جمالش رانظر خورشید تاباں میکند
آفتاب ازرشک حسنش رومی پنہاںمیکند
غزل۔ ۱۶۔ شعر ۔۱۔ چمکتا ہوا سورج بھی جب اس کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے تووہ بھی رشک حسن سے اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے ۔
یاد رہے کہ چہل اسرار کی غزلیں ، معجزاتی طور پر ہی چودہویں صدی کے اخیر میں وجود میں آتی ہیں ۔ لہٰذا جائزہ لیں تو معلوم ہو گا کہ شاہ ہمدان کی غزلوں میں بھی انہیں فنی اور جمالیاتی اقدار کو برتا گیا ہے جن کا رواج اس دور تک کی غزلوں میں ملتا ہے مثلاً
۱ شاہ ہمدان کی غزلوں میں بھی مطلع و مقطع کا اہتمام ملتا ہے بعض غزلوں میں حسن مطلع کے طور پربھی اشعار لائے گئے ہیں۔
۲ شاہ ہمدان کے مقطعے کے اشعار میں بطور تخلص کہیں علائی اور کہیں علی لایا گیا ہے ۔
۳ شاہ ہمدان کی زیادہ تر غزلیں چھوٹی رواں بحروں میں ہیں جس سے قاری کو شعر کی قرأت میں اور مغنی کو نغمہ سنجی میں آسانی ہوتی ہے۔
۴ شاہ ہمدان کی غزلوں میں عام طور پر ترنم خیز رویف و قوافی کا استعمال ہوا ہے جن سے قرأت کے نتیجے میں غنائیت کا اخراج بلا روک ٹوک فطری طور پر ہوتا ہے۔
۵ دیگر شعرا کی طرح شاہ ہمدان کی غزلوں میں بھی اشعار کی تعداد میں یکسانیت نہیں ۔ غزل میں اشعار کی کم سے کم تعداد کسی نے تین کسی نے پانچ بتائی ہے اور زیادہ سے زیادہ گیارہ سے پچیس تک بھی بتائی گئی ہے۔ لیکن یہ سب مفروضات ہیں غالب کے یہاں دوشعر کی غزلیں بھی ہیں اور تین شعر کی بھی شاہ ہمدان کی اکثر غزلیں ۹۔۹ اشعار پر مشتمل ہیں ۔ کم سے کم ۷ ِ اشعار کی غزلیں بھی ہیں اور زیادہ سے زیادہ ۱۵ِ اشعار کی غزلیں ملتی ہیں ۔ اساتذہ کے یہاں غزل کے اشعار کی تعداد طاق رکھنے کی روایت رہی ہے لیکن اس کا کوئی منطقی جواز نہیں ۔ شاہ ہمدان کی غزلوں میں بھی اشعار کی تعداد زیادہ تر طاق ہی ہے لیکن ۱۲ِ اشعار پر مشتمل غزلیں بھی ہیں ۔
۶ شاہ ہمدان کی غزلوں میں بھی ہر شعر معنوی اعتبار سے آزاد حیثیت کھتا ہے ۔ لیکن فکر کی متعین سمت اور شاعری کے طے شدہ مقصد کے سبب علامہ اقبال کی طرح شاہ ہمدان کے بھی اکثر اشعار میں معنوی ارتباط وار تقا کی کیفیت ملتی ہے ۔ اس لیے آج کی زبان میں شاہ ہمدان کی اکثر غزلوں میں بین المتونیت [Intertextuality] بھی ملتی ہے اور متن پر متن قائم کرنے کی مثالیں بھی۔
۷ شاہ ہمدان کی غزلوں کا اسلوب بنیادی طور پر استعاراتی ہے ۔ ایسا اس لیے ہے کہ شاہ ہمدان کو پتہ تھا کہ ’’ غزل کی پہلی اور آخری پہچان اس کی داخلیت ، غیر واقعیت اور بالواسطگی ہے اور غزل میں خارجی فکری اور نظریاتی خیالات و تجربات کو تشبیہہ و استعارہ کی مدد سے ہی بیان کیا جا سکتا ہے ۔ اسی لیے شاہ ہمدان کی غزلوں میں تشبیہات واستعارات کا ایک قابل قدر سرمایہ ملتا ہے ۔
۸ غزل کثرت الفاظ کا نہیں کفایت الفاظ کا فن ہے اور بڑا شاعر وہ ہے جو شعر کی زمین ۔ یعنی بحر ، وزن ، ردیف و قافیہ کی قدر و قیمت ذہن میں رکھ کر کم سے کم الفاظ کے لسانی برتاو سے شعر میں معنی ومفہوم ، کیفیت و تاثر کے زیادہ سے زیادہ امکانات پیدا کرے ۔ شاہ ہمدان کے اشعار میں معنی ومفہوم کی تخم ریزی (Dissmination) کا یہ عمل عمدہ صورتوں میں ملتا ہے۔
۹ شاہ ہمدان کی غزلوں کے متون بھی دو طرح کے ہیں ایک وہ جسے سبقی متن یا Readerly Text کہتے ہیں اور جو قاری کے ذوق اور معیار سے مطابقت رکھتے ہیں ۔ ایسے متون سے قاری وہی معنی و مفہوم اخذ کرتا ہے جو شاہ ہمدان قاری تک پہنچانا چاہتے ہیں ۔ لیکن دوسری طرح کے بعض متون ایسے ہیں ۔ جنہیں تخلیقی متون Writerly Text کہا گیا ہے ۔ ایسے متن معنیاتی اور جمالیاتی امکانات کی ترسیل کے لیے منتخب قاری اور مخصوص قرأت کا تقاضہ کرتے ہیں ۔ چہل اسرار کی کئی غزلوںمیں ایسے متون ملتے ہیں۔
۱۰ شاہ ِ ہمدان کی غزلوں میں ارضیت زیادہ ہے ۔ وہ حق و معرفت کی باتیں شاعرانہ صنعت گری کے ساتھ کرتے ہیں ۔ اکثر مبالغے سے بھی کام لیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے اشعار اتنے پیچیدہ نہیں کہ فہم و فراست سے ماورا ہو جائیں۔
شاہ ہمدان کی غزلوں کے ان عمومی صنفی اور شعری امتیازات کے ذکر کے بعد اگر ان بنیادی خصائص کا جائزہ لیں ۔ جن پر’’ چہل اسرار‘‘ کی عظمت اور معنویت کا انحصار ہے تو دو باتیں سب سے پہلے سامنے آئینگی ۔ اول یہ کہ ’’چہل اسرار ‘‘کی شاعری اسلامی نظریہ جمال کی تابع شاعری ہے جو اسلامی معاشرت اور ثقافت کی تشکیل میں معاون ثابت ہوتی ہے ۔ دوئم یہ کہ گرچہ چہل اسرار ۔ غزلیات کا مجموعہ ہے لیکن اس کی غزلیں اپنے فکری اور معنیاتی نظام کی بنا پر ۔ غزلیہ شاعری کے کلیدی عناصر یعنی حسن و عشق اور رندی و سرمستی کے رسمی اور اصطلاحی مفاہیم کو ترک کر کے شاہ ہمدان کی شاعری کو پاکیزہ مقدس اور تعمیری قلب ماہئیت کی شاعری بناتی ہیں اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں ۔ اسلامی نظریہ جمال کی رُو سے فن کی عظمت و علویت کے لیے فن میں اعلیٰ تعمیری مقصدیت کی موجودگی کو آرائش فن کے لوازمات کے برتاو پر فوقیت حاصل ہے ۔ اگر چہ اعلیٰ تعمیری مقصدیت ہی’’ حُسن اصلی‘‘ ہے لیکن اس حسن کے فنی اظہار کو حسین بنانے کے لے ضروری ہے کہ فنی اور جمالیاتی تقاضوں کو بھی موزونی و کمال اور تناسب و اعتدال کے ساتھ برتا جائے ۔ اس طرح کے تخلیقی روّیہ (Creative Attitude) کے سبب ہی فن میں بو قلمونی ، موزونیت ، جامعیت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔
اسلامی نظریہ جمال کا دوسرا پہلو ’’تخلیق بالحق ‘‘ یا ’’ تخلقو اباخلاق اللہ‘‘ ہے جس کے مطابق فن میں ’’تخیل و تصّور ‘‘ پر تعقل و تفکر‘‘ کو ترجیح حاصل ہے ۔ دوسرے لفظوں میں اسلامی نظریہ جمال کی رُو سے وہی فن یا شاعری اعلیٰ و عمدہ شاعری ہے ۔ جس میں تنظیم و تہذیب سے عاری بے مقصد اور خام جذبات و خیالات کے بجائے منظم مربوط ، مہذب بامقصد اور تعمیری افکار و نظریات کا اظہار کیا گیا ہو ۔ کیونکہ ایسی ہی شاعری نہ صرف یہ کہ صوری و معنوی اعتبار سے حسین و جمیل ہوتی ہے بلکہ انسان کو ظاہری اور باطنی ، انفرادی اور اجتماعی ہر لحاظ سے حسن و خوبی کا پیکر بننے میں بھی ممدو معاون ثابت ہوتی ہے ۔ شاہ ہمدان کی شاعری ایسی ہی شاعری کے زمرے میں آتی ہے ۔ یا دواشت کے لیے صرف دو اشعار سامنے رکھ سکتے ہیں ۔
از ہوائی نفس گریکرہ خلاصی باشدس
در ہوائی لامکان لاف از ملک افزوں زند
غزل ۲۲۔ شعر۔ ۵۔ ہوائے نفس سے اگر دِل خلاصی حاصل کرے تو لامکان کی خواہش میں وہ فرشتوں سے بھی بلند و برتر ثابت ہو گا۔
تو کوئے دوست ہمی جوئی و نمیدانی
کہ گر نظربہ حقیقت کُنی تو آں کوبی
غزل ۔ ۲۸۔ شعر ۔۲۔ تم کوچہ یار کی تلاش میں ہو اور نہیں جانتے کہ در حقیقت خود تمھارے اندر ہی وہ کوچہ ہے یعنی انسان خود اپنے اندر ہی خدا کی تلاش کر سکتا ہے۔
شاہ ہمدان نے ہر طرح کے مضامین اپنی غزلوں میں بیان کئے ہیں اور غزل میں ، حسن و عشق اور آزادہ روی کے ساتھ ہی تصوف بھی بنیادی موضوع رہا ہے۔ گرچہ اسلامی تصوف میں سب سے زیادہ وقعت عشق حقیقی کو حاصل ہے لیکن بعض شعرا کے یہاں عشق حقیقی کو عشق مجازی کے پردے میں پیش کرنے کا جو رجحان ملتا ہے اسکے اپنے غیر اسلامی معاشرتی اور ثقافتی اسباب ہیں ۔ شاہ ہمدان کی صوفیانہ شاعری کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے چند ایک اشعار میں حقیقت کو مجاز کے سانچے میں ڈھال کر پیش کیا ہے لیکن اس طرح کہ مجاز کے آئینے میں حقیقت کا نظارہ کیا سکتا ہے مثلاً
قبلۂ دل آفتاب ِ روئے اوست کعبۂ جاں خاکِ راہ کوئے اوست
چوں زِ زُلفش گشت عالم مشکبوئے دوستیٔ ایں و آں بربوئی اوست
کفرُ دین و نورو ظلمت در جہان ازرُخِ ماہ و شب گسیوئی اوست
غزل ۔۲۔ شعر ۱،۲،۳ ۔ اس کا آفتاب کی طرح روشن چہرہ ، قبلہ دل و جاں ہے اور اس کے کوچے کی گردراہ کعبہ جان و ایمان ہے۔
اس کی زلفوں کی خوشبو سے جب یہ سارا عالم معطر ہو گیا تو اسی خوشبو کے طفیل دنیا ئے محبت و اخوت وجود میں آئی اور دنیا میں کفر و دین اور نور و ظلمت معشوق کے چاند سے چہرے اور سیاہ زلفوں کے سبب ہی وجود میں آئے ہیں۔
دراصل بیرون ہند سے ہندوستان آنے والے صوفیا اور مشائیخ مثلاً خواجہ معین الدین چشتی ، خواجہ فرید الدین گنج شکر ، حضرت نظام الدین اولیا، شیخ عبدالقادر گیلانی ، خواجہ باقی باللہ اور شیخ احمد سرہندی وغیرہ نے الگ الگ علاقوں میں اسلام اور اسلامی تصوف کو اس کے حقیقی خطہ و خال میں برقرار رکھتے ہوئے اس کی توسیع و تبلیغ کی جو کوششیں کی تھیں ۔ کشمیر میں شاہ ہمدان کی شاعری بھی اسی کی ایک شکل ہے ۔ اسلامی تصوف کی رُو سے قربِ الہٰی کا واحد ذریعہ عشق ہے اور وحدت الوجودی عقیدے کے مطابق عشق کی انتہا فنافی اللہ ہے ۔ شاہ ہمدان کی شاعری میں فنافی اللہ کے حوالے سے کثرت سے اشعار ملتے ہیں مثلاً
اگر فانی شوی در بحر تو حید
عیاں بینی کہ آنجا کیف و کم نیست
غزل ۔ ۴۔ شعر ۔۹۔ اگر تم تو حید کے سمندر میں فنا ہو جا و تو بے قیل و قال تم پر سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔
قطرہ، بہ در یا شدہ ، مطلق بجا شدہ بحر محیط قدم ، قید شدہ در حدود
غزل ۸۔ شعر ۔۷۔ قطرہ دریا میں مل گیا اور اس کی وجہ سے بحر محیط کی روانی بھی حدود میں قید ہو گئی۔
جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے شاہ ہمدان کی شاعری غزلیات پر مشتمل ہے اور روایتی معنوں میں غزل کا بنیادی وصف تغزل ہے ۔ عام تصور یہ رہا ہے کہ غزل میں تغزل مخصوص مضامین ، مخصوص لب و لہجہ اور مخصوص زبان کے برتاؤ سے پیدا ہوتا ہے ۔ مخصوص مضامین سے مردا حسن و عشق ، حق و معرفت ، تصوف و اخلاق ، رِندی و سرمستی اور سوز و غم کے مضامین ہیں لیکن متوسطین نے جن میں شاہ ہمدان بھی شامل ہیں۔ رندی و سرمستی جیسے مضامین کو رسمی اور اصطلاحی معنوں میں نہیں بلکہ پاکیزہ اور تعمیری معنوں میں برتا ہے ۔ حافظ ؔ ، سعدی ؔ اور بیدلؔ سے لے کر اقبالؔ تک کے یہاں رندی و سرمستی کے مضامین کے بیان میں مخصوص الفاظ تراکیب اور اصطلاحات کے پاکیزہ اجتہادی معنوں میں استعمال کی مثالیں بھری پڑی ہیں ۔ اسی طرح شاہ ہمدان نے بھی اپنی غزلوں میں ایسے الفاظ و تراکیب کو حق و معرفت کے مضامین بیان کرنے کرنے کے لیے استعمال کر کے تغزل کی ایک مقدس فضا پیدا کی ہے ۔ مثلاً یہ اشعار دیکھئے ۔
چوں در ریاض اُنس شراب بقا چشید خوش تیغ ترک بر رُخ دار الفنا زنند
غزل ۹۔ شعر ۔۸۔ جب وہ گلستان محبت میں شراب بقا کا مزا چکھتے ہیں تو وہ فرط مسرت کی تلوار کو دارالفنا سے ٹکراتے نظر آتے ہیں ۔
بادہ غم نوش اگر خواہی رہا ئی زیں خمار
راہِ رندان گیر گر جوئی تو قرب آنجناب
غزل ۔ ۲۶۔ شعر ۔۶۔ تم اگر مستی و خمار ِ دنیا سے چھٹکارا چاہئتے ہو تو اس کے غم کی شراب پیو ۔ اور اگر تم اس (خدائے بر حق کی) قربت کے خواہاں ہو تو نشہ عشق اِلہیٰ سے سرشار ایسے ہی رندوں کا طریقہ اختیار کرو۔
اسی طرح تغزل کی دوسری شرط یعنی نرم او ردھیمے لہجے کا استعمال بھی شاہ ہمدان کی غزلوں میں کامیابی کے ساتھ ہوا ہے ۔ خواہ الفاظ سے حزنیہ تاثرات پیدا ہوئے ہوں یا نشاطیہ ، بلکہ پاکیزہ اور تعمیری مضمون آفرینی کے لیے بھی جہاں حسن و عشق کے تصورات ایک حد تک مجاز میں پیش کئے ہیں وہاں یہ نرم لہجہ لطیف جذبہ کے ساتھ مل کر ایک دلکش رومانی فضا بھی پیدا کرتا ہے ۔ مثلاً یہ شعر
بوئی ززلف آنمہ بگذشت در دو عالم
ذرات کُون ازآن بوئی سر مست افتادند
غزل ۲۷۔ شعر ۔ ۳۔ میرے محبوب کی زلف سے خوشبو کا ایک جھونکا دونوں عالم میں پھیل گیا ۔ اور اس خوشبو سے کائنات کا ذرہ ذرہ مد ہوش ہو گیا ہے ۔
مخصوص و منفرد زبان کا استعمال صرف تغزل نہیں بلکہ شاعرانہ عظمت و انفرادیت پیدا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے ۔اسی لیے ہر بڑے شاعر کی طرح شاہ ہمدان کی شاعری میں بھی نادر افکار و خیالات کے اظہار کے لیے نت نئے الفاظ کی ایجاد و اختراع اور ان کے فن کارانہ لسانی برتاؤ کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں ۔ اِسی لیے شاہ ہمدان کے دینی اور تعمیری افکار ، شاہ ہمدان کی شاعرانہ حدِت سے پگھل کر شعری تجربہ کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں اور ایسا حسن آہنگ پیدا کرتے ہیں جو شاہ ہمدان کی شاعری کو عظمت و انفرادیت بخشتے ہیں ۔ چنانچہ شاہ ہمدان اپنے جذبہ و احساس ، فکر و خیال اور شعری تجربہ کے اظہار کے حوالے سے نادر الفاظ و تراکیب کا قابل قدر سرمایہ بھی فراہم کرتے ہیں ۔ مثلاً کوئے مفلسی ، آب دیدہ ، صیدشاہین ، زیور ذکر ، سالک راہ وصل ، کعبہ جاں، قبلہ دِل ، نرگس جادو ، بحر توحید ، دُرّ ِ عرفان ، ہمائے قاف ، آتش فراق ، اندوہ اشیتاق ، روضہ وصال، ملامت گاہ عشّاق ، مصردل ، داغ ارادت ، مستان جام شوق ، تیر نیاز غیرہ وغیرہ ،
ان الفاظ و تراکیب کی روشنی میں صرف شاہ ہمدان کی فکری نہج کا ہی نہیں الفاظ کے لسانی برتاؤ اور اظہار کے تخلیقی رویّہ کا بھی بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے ۔ دراصل شعر میں تراکیب کے استعمال کے جتنے بھی فوائد بیان کئے گئے ہیں یعنی اختصار ، جامعیت ، بلاغت اور زور بیان وغیرہ سارے شاعرانہ فوائد’’ چہل اسرار‘‘ کے اشعار میں بہ تمام و کمال سامنے آئے ہیں ۔ اس ضمن میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ شاہ ہمدان کی اکثر غزلوں میں الفاظ و تراکیب کے نادر لسانی وشعری برتاو کے ذریعے صوتی آہنگ پیدا کرنے کی بھی حیرت انگیز مثالیں ملتی ہیں مثلاً چہل اسرار کی بیسویں غزل کے یہ اشعار دیکھئے ۔
از کناِ رخویش می یا بم ویا دم بوئی یار
زاں ہمی گیرم بہردم خویشتن رادرکنار
چوں کنارم رامیانی نیست پیدا ہر زمان
درمیان خونِ دل جانم غمش را کرد کنار
غزل ۲۰۔ شعر ۱۔۲ میں اپنے محبوب کی رعنائیاں ہر وقت اپنے قریب پاتا ہوں اور اسی لیے میں اسکی جانب کھینچا چلا جاتا ہوں ۔
میں ہر وقت اُسے ( اپنے محبوب کو ) اپنے قریب پاتا ہوں اسی لیے اُس سے جدائی کا غم میرے دل میں جاگر یں ہے ۔
شاہ ہمدان کی بعض غزلوں ( مثلاً غزل ۲۔ ۱۰ وغیرہ ) میں مترنم ردیف و قوافی کے التزام سے بھی غنائیت سے بھر پور صوتی آہنگ پیدا کرنے کا رجحان ملتا ہے ۔ اس ضمن میں شاہ ہمدان نے قرآنی آیات ، الفاظ و تراکیب کا استعمال بھی آزادانہ کیا ہے ۔
غرض یہ کہ شاہ ہمدان کی غزلوں کے مجموعے ’’چہل اسرار‘‘ کے لسانی و شعری ، فنی و فکری اور جمالیاتی اسرار کے اور بھی کئی پہلو ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے پھر بھی مندرجہ بالا سطور میں جن چند نکات سے بحث کی گئی ہے ان کی روشنی میں شاہ ہمدان کی شاعری ۔ خاک پائے رسولؐ عربی کی برکتوں سے سرفراز ، ہندوستان آنے والے ان بزرگان دین کی مسلسل اور اجتماعی سرگرمیوں کا ایک حصہ ہے جس کا مقصد بلند و بانگ پہاڑوں ، لق ودق صحراؤں اور ناپیدا کنار دریاؤں پر مشتمل اس برعظیم کو دین مصطفیٰ کے زیر سایہ لاناتھا۔
شاعری ذات کے اندرون میں ٹھاٹھیں مارتے ہوئے جذبہ و احساس ،اور فکر و دانش کے فطری اور بے محابہ اظہار کا نام ہے تو پھر شاہ ہمدان کی غزل بھی اس معشوق حقیقی کے وصل کے ذوق وشوق میں سالک کے اضطراب کسک اور تڑپ کے اظہار سے ہی عبارت ہے ۔ لہذا صوفیانہ اور دینی و تبلیغی مزاج رکھنے کے باوجود شاہ ہمدان کی غزلیں تغزل کی فضا سے معمور ہیں اور فارسی اور اُردو غزل کی شعریات کے جو بنیادی تعمیری امتیازات ہمارے عظیم شعرا کی غزلوں میں ملتے ہیں ان کا سلسلہ کہیں دور کہیں قریب سے شاہ ہمدان کی غزل کی شعریات سے بھی ملتا ہے لہذا سچ تو یہ ہے کہ چودہویں ، پندرہویںصدی میں جبکہ دراوڑی اور آریائی تہذیبوں کے زیر اثر سنسکرت سے لے کر اپ بھرنشوں تک کی شاعری لذت پرستی کی دلدل میں ڈوب چکی تھیں اور برعظیم کی جدید زبانوں میں بھی کنگھی چوٹی بلکہ جنسی لذتیت سے بھر پور شاعری کا رواج عام ہو چکا تھا ایسے میں اگر مسعود سعدسلمان ، بابا فرید ، شرف الدین یحییٰ منیری ، بوعلی شاہ قلندر ، بہاء الدین باجن اور قاضی محمود وغیرہ کے ساتھ ساتھ امیر کبیر شاہ ہمدان کی دینی اور تبلیغی تعمیری شاعری سامنے نہ آئی ہوتی تو آج ہندوستانی معاشرت اور ثقافت میں اسلامی رنگ وبو کے اتنے اور ویسے نظارے بھی نہ ہوتے جتنے اور جیسے نظاروں کے درمیان ہم اور آپ جی رہے ہیں :
قدوس جاوید
بیت الزھرا،۲۷ گرین ہلز کانونی، نزد ۔ گورنمنٹ سکنڈری اسکول
بھٹنڈی ۔ جموں ۔ ۱۸۱۱۵۲، 9419010472