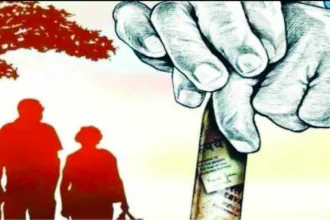برصغیر میں اردو ادب کی دو تاریخ ساز شخصیات سرسید احمد خان (۱۸۱۷ء -۱۸۹۸ء ) اور علامہ محمد اقبال (۱۸۷۷ء -۱۹۳۸ء ) ہیں۔ مذکورہ دونوں متبحّر نابغاؤں نے اپنے افکار و اعمال سے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری علمی دنیا میں ایک علمی تحرک پیدا کیا ۔ برصغیر کے مخصوص حالات کے تحت دین و سیاست کی جدید تفہیم و تعبیر میں مذکورہ دونوں مفکرین میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے اگر چہ کہیں کہیں اختلاف کی گنجائش بھی نظر آتی ہے ۔
یہ دونوں علمی و ادبی شخصیات اپنے عمیق مطالعے اور وسیع مشاہدے کی وجہ سے آخر اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اقوام و ملل کی فلاح، صلاح اور ترقی کا انحصار ایک حرکی (Dynamic)نظام حیات ہی پر منحصر ہے جو جدید مقتّضیات کو بھی پورا کرتا ہو۔ اسی بناء پر یہ دونوں علمی، ادبی اور سیاسی شخصیات برصغیر کے تعلیمی ، اقتصادی ، معاشرتی اور سیاسی نظام کو ہر حیثیت سے ترقی کی راہ پر گامزن دیکھنے کے متمنی تھے ۔
مذکورہ دونوں مسلم نابغاؤں نے اپنی فکری اور علمی تحریک سے اسلام کی تعبیر نو (Modern Interpretation)کر کے برصغیر کے مسلمانوں کو بے یقینی اور تشکیک کے دھندلکے میں روشنی دکھائی ، اگر چہ عام لوگ اسے قریب قریب نظر انداز ہی کر گئے۔ دراصل یہ دونوں شخصیات اسلام کے مثالی دین ہونے پر یقین کامل رکھتے تھے۔ دونوںشخصیات ایک جانب اسلام کی عظیم تعلیمات، روایات سے بہرہ ور تھے اور دوسری جانب عہد حاضر کی سائنسی ترقی اور تجرباتی منہاج کے رمز شناس ۔ اس اعتبار سے انھیں بجا طور پر ہم عالم جدید کی ضرورتوں اور تقاضوں کے مطابق برصغیر میں نہ صرف مسلمانوں کے لئے بلکہ بلا تفریقِ مذہب و ملل تمام لوگوں کے لئے مسیحا قرار دے سکتے ہیں ۔ دونوں کے نزدیک دین اسلام حریت فکر و عمل اور امن و آشتی کا پیغام فراہم کرتا ہے ۔ اس تناظر میں ایک طرف سرسید احمد خان عمر بھر اپنے عالمانہ مکاتیب، تعلیمی نظریات اسکے عملیات اور انقلابی اداریوں کے ذریعے برصغیر میں جدید علوم و فنون کی اہمیت کا درس دیتے رہے او دوسری طرف اقبالؔ اپنی سحر انگیز پیامی شاعری اور مفکرانہ درس و تدریس سے ایک فکری اور علمی انقلاب کے لئے راہ ہموار کرتے رہے۔ یوں ان دونوں نابغاؤ ں نے اسلام کی حقیقی روح کے مطابق زندگی کے عصری تقاضوں کو قبول کرتے ہوئے دینِ اسلام کی ایک حرکی (dynaic)تشریح و تعبیر کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ مسلمان بالخصوص اور عام انسان بالعموم ایک روح پرور آزاد جمہوری نظام سے وابستہ رہتے ہوئے نہ صرف برصغیر بلکہپوری دنیا میں امن و آشتی کے ماحول میں زندگی کی راہ پر گامزن ہو جائیں ۔ یقیناً اِن دونوں نابغاؤں کے پیش کردہ بیش بہا اجتہادی نظریات سے فائدہ اُٹھا کر اب بھی برصغیر علمی، اقتصادی ، معاشرتی اور روحانی فیوض و برکات سے مالا مال ہو سکتا ہے ۔
۱۸۸۴ء میں سرسید احمد خان نے پنجاب کا دورہ کیا اور مسلمانوں کو جدید تعلیم کے حصول کی اہمیت کا احساس دلانے کے لئے کئی تقریریں کیں ۔ پنجاب کے جن گنے چنے افراد پر انھیں خاص اعتماد حاصل تھا اور جن کا وہ کافی احترام کرتے تھے ، اُن میں علامہ اقبال کے اولین اُستاد مولانا میر حسنؔ بھی تھے۔ چنانچہ ۱۸۹۵ء میں جب مسلم ایجوکیشن کانفرنس کا اجلاس لاہور میںمنعقد ہوا تو اس میں انھوں نے بھی شرکت کی ۔
علامہ اقبال کی ابتدائی طالب علمانہ زندگی پر مولانا سید میر حسن (۱۸۴۴ء -۱۹۲۹ء) کی شخصیت حاوی رہی ہے ۔ سید میر حسنؔ بھی سرسید کی طرح ایک روشن فکر اہل علم تھے جو مصلح دین اور مصالح دنیا کو ایک ساتھ پیش نظر رکھ کر شاگردوں کی تربیت کرتے تھے ۔ سید میر حسن مسلمانوں میں جدید تعلیم مقبول کرنے کے لئے کوشاں رہتے تھے، میر حسن کی اسی بہترین تربیت ہی کی نتیجے میں اقبال جہاں اُن کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار یُوں کرتے ہیں ؎
مجھے اقبال اُس سیّد کے گھر سے فیض پہنچا ہے
پلے جو اس کے دامن میں ، وہی کچھ بن کے نکلے ہیں
وہیں آپ سرسید احمد خان کے متعلق اپنی معروف نظم ’’سید کی لوح تُربت‘‘ کے عنوان سے اُن کے پیغامِ عمل سے ہمیں یوں روشناس کراتے ہیں ؎
وانہ کرنا فرقہ بندی کے لئے اپنی زبان
چھُپ کے ہے بیٹھا ہُوا ہنگامۂ محشر یہاں
وصل کے اسباب پیدا ہو، تری تحریر سے
دیکھ کوئی دل نہ دُکھ جائے ترے تقریر سے
محفلِ نومیں پُرانی داستانوں کو نہ چھیڑ
رنگ پر جو اَب نہ آئیں اُن فسانوں کو نہ چھیڑ
علامہ نے ان اشعار میں سرسید احمد خان کے اُس مخصوص طریقِ کار کی طرف اشارہ کیاہے جس میں وہ مسلمانوں کی باہمی فرقہ بندیوں سے بچ بچا کر، اور ہندو مُسلم تنازعات کو چھیڑے بغیر مسلمانوں کی ترقیوں کے لئے کام کرنے میں کوشاں رہے ۔
معروف ماہر اقبالیات پروفیسر عبدالحق کے بقول لوحِ تُربت کی اس تحریر میں بہت سے اسرار کندہ ہیں مگر ایک نکتے کے حروف قدرے جلی ہیں ۔ وہ سرسید کو عزیز، اقبال کو عزیز تر اور ہمارے لئے سامانِ زیست ہیں۔ وہ حروف ہیں ؎
مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین
ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں
دراصل علامہ اقبال اسلام سے متعلق سرسید احمد خان کی انقلاب انگیز تحریروں سے ابتداء ہی سے آشنا تھے اور اُن کے مداّح بھی تھے لیکن جہاں تک سرسید احمد خان کے بعض مذہبی اور سیاسی افکار کا تعلق ہے ، وہ سمجھتے تھے کہ ان میں اصلاح کی گنجائش ہے ۔ قدامت پسند علماء شروع ہی سے سرسید احمد خان کے خلاف تھے ۔ اُن کی نگاہ میں جو کوئی بھی وقت کے جدید تقاضوں کے مطابق علم کلام یافقہ کی تعبیر جدید کی ضرورت کا ذکر چھیڑتا، وہ بدعتی اور مغرب زدہ قرار پاتا۔ لہٰذا اقبال نے اپنی ملی شاعری کے ابتدائی مراحل ہی میں بعض نظموں میں ایسے علماء کو تضحیک کا نشانہ بنایا تھا، کیونکہ اُن کے نزدیک کم علم ملاؤں کا طبقہ ہندوستان میں اسلامی ترقی کو ضعف پہنچا رہا تھا۔ چنانچہ انگریز دوستی کے الزامات کے سلسلے میں جو تہمتیں اور افترابازیاں سرسید احمد خان پر باندھی گئیں بعد میں جب اقبال بہت سارے اجتہادی معاملات کے سلسلے میں اُنہی کے مکتبہ فکر سے وابستہ ہو گئے ، تو انھیں بھی اُنہی الزامات کا سامنا کرنا پڑا ۔ سرسید احمد خان اور اقبال دونوں نہ صرف اسلام کے آفاقی نظام پر غیر متزلزل ایمان رکھتے تھے بلکہ اسی کو عہد حاضر کے ہر چلینج سے نپٹنے کا ذریعہ بھی سمجھتے تھے ۔
۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد اسلامی عقائد کے سلسلے میں سرسید کو نئے نئے چلینجوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں خاص طور پر جدید سائنسی اکتشافات اور اُن کے فلسفیانہ نتائج اسلامی عقائد کے لئے زیادہ پریشان کن چلینچز تھے ۔ ان حالات میں سرسید نے عقلی استدلال سے مذہب کے معاملے میں کام لینے میں شاہ ولی اللہ دہلوی ؒ کی تقلید کی ۔ مذہبی اصلاح کے لئے اُن کے دو بنیادی خیالات وہی ہیں ۔ جو شاہ ولی اللہ کے تھے ۔ پہلا یہ کہ مذہبی فکر و عمل میں سلف کی تقلید کافی نہیں بلکہ ہر دور میں زمانے کے تقاضوں کا خیال کرتے ہوئے اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے ۔ دوسرا یہ کہ مذہب اسلام کی تعلیم کو عالم انسانیت کیلئے قابل فہم بنانے کی خاطر عقلی انداز میں پیش کرنا ضروری ہے ۔ سرسید کواس ضرورت کا احساس اس لئے ہوا کہ اُن کے زمانے میں رائج اسلامی کتابیں ، مغربی فلسفہ اور علوم جدیدہ کے مسائل کی تردید یا تطبیق کے لئے تیار نہیں کی گئی تھیں ۔ دوسری طرف آپ علوم جدید کے زبردست حامی تھے۔ اپنے خطوط میں آپ صاف کہتے ہیں کہ ’’علوم جدیدہ کی غلطیوں اور نارسائیوں کو پاک کر کے ہم مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں ۔ ‘‘
آپ نظریۂ اجتہاد کے نہ صرف قائل و معترف تھے بلکہ انھوں نے عملاً اجتہادات کئیے ہیں ۔ چنانچہ ایک جگہ آپ تحریر کرتے ہیں :
میں صاف کہتا ہوں کہ اگر لوگ تقلید نہ چھوڑیں گے اور خاص اس روشنی کو جو قرآن و احادیث صحیحہ سے حاصل ہوتی ہے، نہ تلاش کریں گے اور حال کے علوم سے مذہب کا مقابلہ نہ کریں گے تو مذہبِ اسلام ہندوستان سے معدوم ہو جائے گا۔ اسی خیر خواہی نے مجھے برانگیختہ کیا ہے جو میں ہر قسم کی تحقیقات کرتا ہوں اور تقلید کی پرواہ نہیں کرتا۔‘‘
اسی راہ پر گامزن رہتے ہوئے علامہ اقبال پیامی شاعری کے علاوہ اپنے معروف انگریزی خطبات پر مبنی کتاب "The Reconstruction of Religious Thought in Islam" جو ۱۹۳۰ء میں شائع ہوئی واشگاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ:
"The task before the modern Muslim is therefore immense. He has to rethink the whole system of Islam without breaking with the past. Perhaps the first Muslim who felt the urge of a new spirit in him was Shah Waliullah of Delhi.’’
اسی لیکچر میںپھر ذرا آگے چل کر بالکل سرسید کی طرح یہ اعلان کرتے ہیں کہ :
" The only course open to us is to approach Modern knowledge with a respectiful but independent attitude and to appreciate the teachings of Islam in the light of that knowledge, even though we may be led to differ from those who have gone before us."
علامہ اقبال کے متذکرہ بالا خطبات پر مشتمل کتاب میں جو حوالے پیش کئے گئے ہیں یہ دراصل سرسید احمد خان کے اُس خیال کی تائید میںہیں ،کہ اب مسلمانوں کو ایک نئے علم الکلام کی ضرورت ہے اور عصر حاضر کے علوم یقیناً معرفت الٰہی میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں ۔ علامہ اقبال نے اپنی متذکرہ کتاب کے پیش لفظ میں صاف طورپر کہا ہے کہ مذہب اور سائنس کے مابین مماثلتیں زیادہ ہیں اور مذہب سائنس سے بھی زیادہ عقلی ہے ۔ اور یہ ہر لحاظ سے ایک انقلابی فکر ہے ‘‘۔
ڈاکٹر محمد علی صدیقی کے مطابق جس طرح غزالی نے یونانی فلسفے کی عقلی اور غیر تجرباتی اساس کی مخالفت کی تھی اور اس طرح اسلامی علم الکلام کو ایک نیا موڑ دیا تھا، سرسید احمد خان نے بھی اور اُن کے تتبع میں علامہ اقبال نے بھی سائنس کے حق میں پانسہ پھینک کر اسلامی دنیا میں غور و فکر کا ایک نیا دروازہ کھول دیا ہے ۔ میرا خیال ہے کہ مستشرقین میں خصوصیت کے ساتھ رینان نے اسلام اور سائنس میں عدم مطابقت کو جس شدو مد کے ساتھ بیان کیا تھا،۔ سرسید اور اقبال نے اسلام اور سائنس میں مطابقت کو اُسی قدر شدو مد کے ساتھ لازم و ملزوم ٹھہرایا۔‘‘
دراصل علامہ اقبال کے یہاں سرسید احمد خان کی فکر میں موجود Work of God and Act of Godکی یکجائی اس طرح نظر آتی ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف مراجعت کر رہی ہے اور اس طرح سائنس بھی معرفتِ مشیت الٰہی بن جاتی ہے نہ کہ اس کی نقیض ۔ لہٰذا ہم بزبان اقبال اور سرسید کہہ سکتے ہیں کہ جدید علوم کا حصول معرفت الٰہی میں اضافہ کا سبب بن سکتا ہے ۔
سرسید احمد خان جدید ساینس کا مطالعہ مسلمانوں کے لئے از حد ضروری خیال کرتے تھے اس لئے اُن کے نزدیک اسلامی نظریات کی تشریح روایتی انداز میں کرنے کی بجائے نئے اور بدلے ہوئے زوائیے نگاہ سے کرنا لازمی ہے ۔ اس کے علاوہ عیسائی مشنریوں کے اسلام پر حملے نے اُنہیں مدافعانہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ عیسائی مشنریوں کا استدلال عموماً یہ ہوتا تھا کہ اسلام ایک غیر عقلی مذہب ہے جو انسان کے تمدنی ارتقاء کا مخالف ہے۔ سر سید کی رائے میں جدید سائنس چونکہ تجربہ و مشاہدہ پر مبنی ہے ، اس لئے دہریت کی طرف لیے جاتی ہے لیکن اگر جدید سائنس کی تحقیقات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کی تشریح سے متعلق نیا علم الکلام ترتیب دیا جائے تو مسلمان اسلام کو زندگی کے جدید تقاضوں کے عین مطابق پائیں گے اور اسلام پر ان کا ایمان مضبوط ہو گا۔ اُن کے نزدیک اسلام ایک فطری یا نیچری مذہب تھا، کیونکہ جدید سائنس جن نتائج پر پہنچی ہے ، وہ بہت حد تک قرآنی تعلیمات سے ہم آہنگ ہیں۔
علامہ اقبال بھی اُنہی کی طرح فکر اسلامی کی تشکیل جدید کے متمنی دکھائی دیتے ہیں ۔ آپ عہد حاضر کے سائنسی افکار کو اسلامی حکمت و تدبر کے حوالے سے اور اسلامی حکمت کے کچھ نمایاں مسائل کو مغربی افکار کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کا استدلال یہ ہے کہ ’’میرا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا مذہبی فلسفہ اس انداز میں پیش کیا جائے کہ اسلام کی فلسفیانہ روایات کو بھی ملحوظ نظر رکھا جائے اور انسانی افکار کے جدید انکشافات و اختراعات سے بھی ثبوت مہیا کئے جائیں ۔ ہمارا فرض ہے کہ فکر انسانی کے ارتقاء پر نظر رکھیں اور آزادانہ تنقیدی اسلوب قائم کریں ‘‘۔
……………………….
رابطہ :اسسٹنٹ پروفیسرریسرچ اینڈ کارڈی نیٹر اقبال انسٹی آف کلچر اینڈ فلاسفی،کشمیر یونیورسٹی
(بقیہ منگلوار کے شمارے میں ملاحظہ فرمائیں)