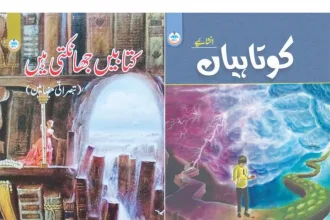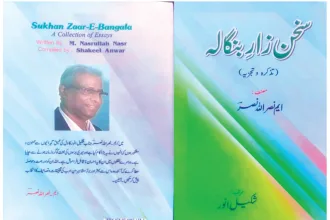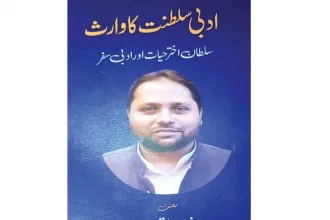ادب ایک وسیع موضوع ہے۔نظم ہو یا نثر کی متعدد اصناف ہیں۔ اس پہ برابر تب تک لکھاجائے گا جب تک زمین پر انسان آباد ہے۔ سائنس کی ترقی آسمان کو بھی چھوئے اور تیکنالوجی انسان کا اوڑھنا بچھونا بن جائے مگر ادب کی اہمیت باقی رہے گی۔ ہمارے عزیز دوست ڈاکٹر منصور احمد منصور صاحب لکھتے ہیں: ’فن کار خارجی ماحول کی پیش کش تک ہی محدود نہیں رہتا۔ یہ کام تو مورخ کا ہے کہ ’’جو ہے‘‘ اسے پیش کرے۔ فن کار ’’جو ہے‘‘ کو مضبوطی سے گرفت میں لے کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کردیتا ہے اور اسے نفس کی بھٹی میں تپاکر ہی پیش کرتا ہے، یعنی نفس کی بھٹی میں پڑکر خارجی تجربات ومشاہدات وقت گزرنے پر داخلی کوئف بن جاتے ہیں۔ سائنسی مشاہدہ بھی خارجی ہوتا ہے اور سائنس بھی حقیقت تک رسائی کے لئے تجزیہ کاطریقہ اختیار کرکے زندگی کو ٹکڑے ٹکڑے کرکے زندگی کے قوانین سے آگاہی حاصل کرتا ہے، لیکن سائنس میں جذبہ و احساس کا دخل نہیں لیکن ادب کی روح یہی ہے کہ اس میں خارجیت کے ساتھ داخلیت بھی ہے۔ فلسفہ میں فکر کا پلڑا بھاری ہے اور یہاں بھی ’’دل نہیں بلکہ دماغ‘‘ کام کرتا ہے۔ ادب میں دل بھی دھڑکتا ہے اور ذہن بھی پھڑکتا ہے۔ ‘‘
معروف ادیب جناب مجتبیٰ حسینؔ کا کہنا ہے: ’’جب بھی انسان کے قلب پر چوٹ لگتی ہے یا ٹھیس پہنچتی ہے اور اس ٹھیس اور چوٹ کے بعد جو خیالات، جذبات اور تاثرات فن کار صفحۂ قرطاس پر ترقیم کردیتا ہے وہی وقیع اور اعلیٰ مزاح ہوتا ہے‘‘۔
مجھے مجتبیٰ حسینؔ کے ان خیالات سے بھرپور اتفاق ہے۔ تاہم بات کو تھوڑا سا اور بڑھانے کی جسارت کررہا ہوں۔ غم و حزن کی صد مزاح وظرافت ہے اور میرایہ تجربہ ہے کہ یہ المیہ کے بعد ہی اُبھرتا ہے۔ جب دل پر صدمات کی بوچھاڑ ہوجاتی ہے اور آدمی اپنی شخصیت کو بکھرنے سے بچا پاتا ہے ، اِس کے باوجود کہ اندر ہی اندر ریزہ ریزہ ہوتا رہے، تو پھر اِس ہمت کے انعام میں قدرت ایسے آدمی کے اندر مزاح کی حِس پیدا کردیتی ہے۔ اب اگر ایسے آدمی میں لکھنے کا ہنر بھی ہو تو طنز نگار اور مزاح نگار بھی بن جاتا ہے۔ یہاں ایک ایسے پرندے کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا جس کے بارے میں خیال ہے کہ عرب کے وسیع صحرائوں میں پایا جاتا ہے۔ بہرحال اس جانور کی کوئی حقیقت بھی ہے یا کہ کوئی تصوراتی پرندہ ہے مگر میرے موضوع کے موافق ضرور ہے۔بتایا جاتا ہے کہ اِس پرندے کو ایک خاص قسم کے زہریلے سانپ کی تلاش رہتی ہے اور اِس کی طلب میں صحرا صحرا بھٹکتا رہتا ہے۔ پھر کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں اسے یہ مل ہی جاتا ہے اور کھالیتاہے، مگر اس کا زہر اسے تڑپادیتا ہے اور یہ سخت قسم کی بے چینی اور درد میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ اسے شدید پیاس لگتی ہے اور یہ پانی کی تلاش میں نکلتا ہے۔ بہت تلاش اور سفر کے بعد اسے پانی تو مل جاتا ہے مگر اپنی جبلت سے اسے خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ پانی پینے سے مرجاؤں گا۔ اس کا یہ سوچنا صحیح بھی ہے ،پانی پینے سے اس کی موت واقع ہوسکتی ہے، چنانچہ یہ پیاس سے تڑپتا رہتا ہے مگر پانی نہیں پیتا۔ درد کی شدت جب بڑھ جاتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں جس سے اس کا درد دھیما ہوجاتا ہے اور اسے آرام وسکون ملتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے نیچے دو گڑھے سے بنے ہوتے ہیں۔ اس کے یہ آنسو ان ہی گڑھوں میں جمع ہوجاتے ہیں جو پھر منجمد ہوکر دو انمول قسم کے موتے بن جاتے ہیں۔
یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ المیہ کے دباؤ اور صدمات کی کیفیت میں کبھی مزاح نہیں اُبھرسکتا بلکہ جب ان صدمات کی شدت دھیمی پڑجاتی ہے اور انسانی ذہن کو قرار سا مل جاتا ہے تو مزاح پنپنے اور اُبھرنے لگتا ہے۔ ایسا شخص کسی واقعے یا بات کو لفظوں کی کانٹ چھانٹ سے مزاح کا رنگ دے کر پیش کرنے کا سلیقہ اور طریقہ خود ہی سیکھ لیتا ہے۔ دراصل شدید صدمات سے گزرنے والا آدمی لاشعوری طور خود ہی اپنے آپ میں المیہ کا توازن مزاح سے برقرار رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔،پھر جب وہ اپنے بیانات یا اظہار کو مزاحیہ صورت میں پیش کرتا ہے تو دوسرے حساس اذہان اپنے اپنے اعتبار اور استعداد کے مطابق ا س سے لطف لینے لگتے ہیں۔
میرا ماننا ہے کہ مزاح سے انسان تب تک لطف نہیں لے سکتا جب تک کہ اُس کا دل ودماغ اس کے لئے آمادہ نہ ہو۔ یہ آمادگی انسان کے دماغ میں مزاح کے لئے ایک سازگار ماحول پیدا کرتی ہے اور تب ہی انسان مزاح سے حظ اٹھانے لگتا ہے۔ ورنہ کسی کا بچہ بیمار ہو یا کسی کی ماں فوت ہوئی ہو یا کوئی بھوکا ہو یا کوئی درد سے تڑپ رہا ہو اور دوسرا اُسے مزاح سنانے لگے تو اثر اُلٹا ہوگا یا ردعمل میں برہمی اور بیزاری ظاہر ہوگی۔
انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ درد وغم سے بچنا چاہتا ہے اور اسی لئے خوشیوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ درد وغم سے اس کی نسیں سکڑ جاتی ہیں اور وہ بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے جب کہ مسرت اور بشاشت سے یہ نسیں نرم پڑجاتی ہیں اور وہ راحت محسوس کرتا ہے۔انسان ہنسنا چاہتا ہے کیونکہ ہنسنا بھی ایک قسم کی سٹریس تھریپی ہے۔ تاہم زیادہ ہنسنے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے کیونکہ اسے دل مردہ ہوجا تا ہے، اور احقر کا یہ ذاتی تجربہ بھی ہے کہ اگر انسان زیادہ ہنستا ہے تو پھر دل میں ایک طرح کی ظلمت محسوس ہوتی ہے اور جو ہنستا ہی نہ ہو وہ تو کوئی شدید ڈپریشن کا شکار آدمی ہی ہوسکتا ہے۔
ہنسنے مسکرانے کے پیچھے کون سے عوامل کا فرما ہوتے ہیں، اس پر لوگ مختلف الخیال ہیں ، کوئی متفقہ فیصلہ نہیں۔ تاہم یہ بات سب جانتے ہیں کہ مزاح سے انسان کو فرحت محسوس ہوتی ہے۔ مزاح کی حِس جس آدمی میں ہوتی ہے وہ ذہین بھی ہوتا ہے۔ یہ بات بھی تسلیم کی گئی ہے کہ ہنسنا بھی انسان کو جانوروں سے ممتاز بنادیتی ہے کیونکہ جانور ہنستے ہی نہیں ۔ ضروری نہیں کہ مزاح سے ہر آدمی کو دلچسپی ہو تاہم جو اسے بالکل پسند نہیں کرتا وہ ذہنی طور دُرست قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ ایسا شخص انسانی صفات سے خالی ہوگا۔ کند دماغ والا بھی ظرافت کا لطف نہیں اٹھا پاتا۔ یہ جو کچھ لوگوں کو بات بات پر ہنسنے کی عادت ہوتی ہے وہ بھی ظرافت کا صحیح لطف نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وقت بے وقت کا ہنسنا انسان کو بے وقار بنا دیتا ہے اور کم عقلی کی دلیل مانی جاتی ہے۔ ایسی عادت ہنسی کو لطف کے اظہار کے بجائے میکانکی عمل بنادیتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کوئی مزاح زیادہ پسند کرتا ہے اور کوئی کم۔ لوئسؔXII جس نے فرانس پر ۱۴۹۸ سے ۱۵۱۵ء تک حکومت کی وہ لطیفوں کو بہت پسند کرتا تھا ۔جب کہ لوئسؔ XIV جس کی فرانس پر ۱۶۴۳ سے ۱۷۱۵ء تک حکومت رہی، نے پوری زندگی میں ایک لطیفہ سنایا ہے۔
ظرافت اور مزاح پر بات کرتے ہوئے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب ؒ فرماتے ہیں:
’ظرافت ومزاح انسانی زندگی کا ایک خوش کن عنصر ہے اور جس طرح اس کا حد سے متجاوز ہونا نازیبا اور مضر ہے اسی طرح آدمی کا اس سے بالکل خالی ہونا بھی ایک نقص ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر کسی بلند پایہ اور مقدس شخصیت کی طرف سے چھوٹی اور معمولی حیثیت کے کسی آدمی کے ساتھ لطیف ظرافت ومزاح کا برتاو ہو تو وہ اس کے لئے عزت افزائی کا باعث ہوتاہے جو کسی دوسرے طریقہ سے حاصل نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے رسول اﷲﷺ بھی کبھی کبھی اپنے جاں نثاروں اور نیازمندوں سے مزاح فرماتے تھے اور یہ ان کے ساتھ آپﷺ کی نہایت لذّت بخش شفقت ہوتی تھی لیکن آپ کا مزاح بھی نہایت لطیف اور حکیمانہ ہوتا تھا۔
ظرافت کا تین طرح سے اظہار ہوتا ہے :(۱) لفظی (۲) مرئی (۳) بدنی۔
اصل میں یہ غم ہی ہے جو خوشیوں کو اہمیت دیتا ہے۔ ڈاکٹر یوسف سرمستؔ لکھتے ہیں اور خوب لکھتے ہیں:’’انسان روتا ہوا آتا ہے اور رلاتا ہوا جاتاہے!‘‘
ظرافت کے تین درجے ہیں:(۱) طنز (۲) مزاح (۳) ہجو
طنز میں جارحیت اور اذیت کوشی کاعنصر ملتا ہے۔
مزاح میں اِس کے برعکس پیار اور انسان دوستی پائی جاتی ہے۔
ہجو میں ملامت، مذمت اور نفرت ظاہر ہوتی ہے۔
جب ہجو کا کسی ذات کے ساتھ تعلق ہو تو پھر اِس کا تعلق ظرافت سے ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر کسی معاشرے یا ادارے پر ہجو گوئی ہو تو اعلیٰ ظرافت میں شمار ہوتی ہے۔مزاح میں الفاظ کے مفہوم اور فقروں کی ساخت کی کانٹ چھانٹ سے ظریفانہ صورت حال پیدا کی جاتی ہے۔ ۔ فرائیڈؔ کہتا ہے کہ ظرافت سے جذباتی کشمکش مٹ جاتی ہے۔ ظرافت پر اپنے خیالات ظاہر کرتے ہوئے وہ آگے کہتا ہے کہ لاشعوری واردات منتشر صورت میں موجود ہوتے ہیں اور مذاق کرنے والا واردات کا یہ تعلق پاتا ہے اور یہ تعلق مذاق کا مرکزی نقطہ بن جاتا ہے۔ اگر ظرافت کا کثرت سے استعمال کیا جائے تو بدمزہ بن جاتی ہے اور کچھ دیگر چیزوں سے بھی بعض اوقات ظرافت سے حماقت ٹپکتی ہے۔
خواجہ حسن نظامیؔ کے انشائیے پڑھنے کے لائق ہیں۔ وہ لفظ اور واقعہ کے بندھن سے ’طنز ومزاح‘ پیدا کرتے ہیں اور پھر اِسی آڑ میں درس بھی دیتے ہیں اور وہ بھی کچھ ایسی مہارت سے کہ قاری کوذہنی مشقت میں نہیں ڈالتے۔ اپنی بات نہایت سہل انداز میں سناتے ہیں۔ ’’جھینگرا کا جنازہ‘‘ میں یوں بات کرتے ہیں: ’’ایک اس مرحوم کو میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عربی ؒکی فتوحات مکیہ کی ایک جلد میں چھپا بیٹھا ہے۔ میں نے کہا کیوں اے شریر! تو یہاں کیوں آیا؟ اچھل کر بولا ذرا سا مطالعہ کرتا تھا۔ سبحان اﷲ! تم کیا خاک مطالعہ کرتے تھے؟ بھائی یہ تو ہم انسانوں کا حصہ ہے۔ بولا: واہ! قرآن نے گدھے کی مثال دی ہے کہ لوگ کتابیں پڑھ لیتے ہیں مگر نہ ان کو سمجھتے ہیں نہ ان پر عمل کرتے ہیں۔ لہٰذٰ وہ بوجھ اٹھانے والے گدھے ہیں جن پر علم وفضل کی کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے‘‘۔
بے ثمر باتوں اور بے ہودہ جملوں سے کسی انسان کو ہنسایا بھی جائے اور ایسی باتوںکو ظرافت کی عبارت میں لایا جائے تو یہ جہاں ادب کی حق تلفی ہوگی وہاں یہ انسانیت سے تشدّد کے بھی مترادف ہوگا۔ ظرافت کا منصب یہ ہے کہ اسے اپنی نزاکتوں، نفاستوں اور لوازمات کے ساتھ با مقصد بنایاجائے۔
مجھے رفیع اﷲ خان عنائیتیؔ کی یہ بات بھی پسند ہے جس میں وہ طنزنگاری کے حوالے سے کہتے ہیں: ’’طنز نگار میری نظر میں ایک سماجی مصلح ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ایسا ’’شعلہ‘‘ ہے جس سے وہ سارے خس وخاشاک جلاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ایسی ننگی ’’شمشیر‘‘ ہے جن کی مدد سے وہ مظلوموں اور محنت کشوں کی صف سے آگے نکل کر ظالموں اور حملہ آوروں پر وار کرتا ہے اور ان کو ہر آن پسپا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ‘‘۔ میں مشتاق احمد یوسفیؔ کے اس خیال کی تائید نہیںکرتا کہ مزاح نگار کے لئے نصیحت، فضیحت اور فہمائش حرام ہیں۔
ایک صاحب علم لکھتا ہے کہ طنز کرنے والے میں دوسروں کو اذیت دے کر خوش ہونے کا میلان موجود ہوتا ہے۔ ایسا شخص خود دلی مسرت اور سکون سے محروم ہوتا ہے اس لئے ہمہ وقت دوسروں کو بھی خوشی اور سکون سے محروم کرنے میں کوشاں رہتا ہے۔ اس کی گفتگو میں تلخی ہوتی ہے، سنک ہوتی ہے اور جارحیت ہوتی ہے۔ وہ ایک پھبتی سے ایک فقرہ چست کرکے مخاطب کو شکست دینے کی تاک میں رہتا ہے۔ جب اس کوشش میں کامیاب ہوجاتا ہے تو اسے اپنی فاتحانہ برتری کا احساس ہوتا ہے۔ طنز کرنے والے اپنی غیر معمولی ذہانت اور درّاکی کے باوجود بالعموم تنگ دل، تنگ نظر اور کم ظرف ہوتے ہیں۔ مزاح میں انسان دوستی کا عنصر لازماً موجود ہوتا ہے جس کے باعث اس میں طنز کی تلخی پیدا نہیں ہوتی۔ آگے یہ صاحب علم کہتا ہے:جو انسانی کمزوریاں طنزومزاح کا ہدف بنتی ہیں ان میں تین مغالطے ایسے ہیں جن سے کوئی بھی انسان بری نہیں ہے۔(۱) میں دنیا کا سب سے عقلمند آدمی ہوں۔(۲) میں دنیا کا حسین ترین آدمی ہوں۔(۳) میں دنیا کا سب سے اچھا آدمی ہوں۔
ہماری اکثر کمزوریاں ان ہی کی فروع سمجھی جاسکتی ہیں۔ طنزیہ اور مزاحیہ شعروادب میں جن کمزوریوں کا خاکہ اُڑایا گیا ہے ان میں شیخی خوری، خودنمائی، باتونی ہونا، ڈینگیں مارنا، اپنی بہادری کا سکہ جمانا، مرد کا ہرجائی پن، عورت کی نشتر زبانی، پیٹ کا ہلکا ہونا، زن مریدی، لالچ، بخل، انانیت، ناشکرا پن، خود غرضی، زرپرستی، بوڑھاپے کا عشق، عورت کے سدا جوان رہنے کی کوشش، ریا کاری، زہد فروشی، شادی کے مزاحیہ پہلو وغیرہ۔ مزید وضاحت کے لئے ہم چند مطائبات درج کریں گے۔
نائی بڑے باتونی ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک نائی نے حجامت بنانے سے پہلے آر کی لوگس شاہ مقدونیہ سے پوچھا:’’جہاں پناہ! حضور کی حجامت کس وضع کی بنائوں؟‘‘
’’خاموش وضع کی‘ ‘بادشاہ نے جواب دیا۔
فارسی اور اردو کے شاعروں نے بعض اوقات صنعت تجنیس سے لطافت وظرافت پیدا کی ہے ،اس صنعت میں دو الفاظ تلفظ میں مشابہ اور معنی میں مختلف ہوتے ہیں۔ غلام علی آزاد بلگرامی نے ایک شعر میں عورت پر چوٹ کی ہے:
زن بود در زبان ہندی نار
وَقِنا رَبَّنا عَذابَ النّار
لفظ نار میں صنعت تجنیس ہے۔ عورت پر کیسے لطیف پیرائے میں چوٹ کی گئی ہے۔ترکی کا ایک شاعر غزائی خان کچھ مدت ایران میں مقیم رہا۔ ایک رباعی میں ایران کے سیاسی استبداد پر طنز کرتے ہوئے کہتا ہے ؎
تابو دہ غم وشادی وحرماں بودہ
زینگو نہ گزشتہ تاکہ دوراں بودہ
ما تجربہ کردیم کہ در ملک شما
راحت ہمہ در حلقہ وزنداں بودہ
کہتا ہے کہ ایران میں اگر کہیں سکون وعافیت ہے تو وہ صرف قید خانوں میں ہے اس میں شک نہیں کہ جس ملک میں جورواستبداد کا دورہ دورہ ہو وہاں بااصول اور شریف انسان کا اصل مقام قید خانہ ہی ہوتا ہے۔
زرپرستی کی ایک مثال اقلیدسؔ کے سوانح میں ملتی ہے۔ ایک دن ایک رئیس زادہ ہندسہ سیکھنے کے لئے اقلیدسؔ کے پاس آیا۔ اقلیدسؔ نے اسے ہندسہ کی پہلی شکل سکھائی۔ رئیس زادہ کہنے لگا: ’’اس کے سیکھنے کا عملی فائدہ کیا ہوگا‘‘؟
اقلیدسؔ نے غلام کو آواز دی،’ ’گرومیو! ان صاحبزادے کو ایک اشرفی دے کر رخصت کردو‘‘۔
حاضر جوابی کی ایک عمدہ مثال مجدالدین کی ’خارستان‘ میں ہے۔
’مولانا قطب الدین نے ایک احول (بھینگا) سے پوچھا، کیا یہ صحیح ہے کہ بھینگے کو ایک کے دو دکھائی دیتے ہیں؟
’صحیح ہے کیونکہ میں مولانا کو چہار پایہ دیکھ رہا ہوں‘۔
مولیرؔ اور والٹیرؔ نے پادریوں کی دکان آرائی اور گندم نما جوفروشی کو خاص طور سے تمسخر و تضحیک کا نشانہ بنایا۔ والٹیرؔ کا کہنا ہے کہ نیکی ظاہری رسوم عبادت کی پابندی کا نام نہیں ہے بلکہ ہمدردی انسان میں ہے۔ والٹیرؔ کی ایک کہانی ہے ’’بابا بیگ‘ ‘جس میں اومنی برہمن سے پوچھتا ہے:
’’کیا یہ ممکن ہے کہ میں انیسویں بہشت تک پہنچ جائوں‘‘؟
برہمن نے کہا:’ ’اس کا انحصار تو اس بات پر ہے کہ تم کس قسم کی زندگی گزارتے ہو‘‘۔
’’میں ایک اچھا شہری ہوں، ایک اچھا شوہر، ایک اچھا باپ، اور اچھا دوست بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ بعض اوقات میں امراء کو بلا سود قرضہ بھی دے دیتا ہوں۔ غریبوں کی امداد بھی کرتا ہوںاور پڑوسیوں میں امن قائم کرتا ہوں‘‘
برہمن کہنے لگا: ’’لیکن کیا تم کبھی کبھار تپسیا میں ننگے بدن کیلوں کے بستر پر بھی لیٹتے ہو‘‘؟
’’نہیں مقدس باپ‘‘
برہمن نے کہا:’’افسوس کہ تم انیسویں بہشت تک کبھی نہیں پہنچ سکو گے‘‘۔
میں ایک عام سا ادیب ہوں۔ جو کچھ دل سے اُبھرتا ہے، کاغذ پر اُتارتا ہوں۔ سیدھی سادھی باتیں ہیں جو میری تحریروں کا مواد ہے، لفظوں کے موتی نہیں کہ صفحۂ قرطاس پر ٹانکنے لگوں۔ محبت کے لئے زندگی بھر ترستا رہا، کہیں ملی نہیں، اب دکھ درد بانٹنے نکلا ہوں!!!
ؕ����