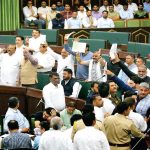دنیا بھرمیں اردو زبان سے پیار کرنے والے ،اسے بولنے والے اور لکھنے والے پائے جاتے ہیں مگر ہمارے یہاں صرف اس کے دشمنوں کی بہتات ہے۔ ریاست جموں و کشمیر میں اردو کا سنیری دور ڈوگرہ حکمرانوں سے شروع ہوا۔اس سے پہلے کشمیر میں فارسی زبان کو سرکاری حیثیت حاصل تھی۔ 1846ء میں ڈوگرہ اقتدار کشمیر کامقدر بنا اور مہاراجہ گلاب سنگھ نے اپنی سلطنت کی توسیع کرتے ہوئے لداخ، کشتواڑ اور چناب وادی کے سبھی اضلاع پر حکومت کی۔ اس حکومت کی سرکاری زبان ابتداء میں فارسی تھی مگر پھر اردو کو رواج ملا ۔ اردو کی ترقی کا آغاز تیرہویں صدی سے شروع ہوا، جلد جلد ترقی کی منزلیں طے کرتی ہوئی یہ بھارت کے مختلف مذاہب کی زبان بن گئی۔اس زبان کی ترقی و ترویج کے لئے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ چند عظیم ہندو ادیبوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔اس زبان کی آبیاری میں شمالی ہند کے تقریباً تمام علاقوںنے اپنا حصہ ڈالا۔ دھیرے دھیرے یہاں کے لوگ اسے دکن میں لے گئے جہاں دکنی اور گجراتی زبان کہلائی۔ اردو زبان کے فروغ میں حیدرآباد دکن اور پنجاب کی خدمات اتنی اہم ہیں جتنی دہلی اور لکھنو کی۔ خصوصا ًپنجاب نے اردوکے علمی و ادبی خزانوں میں بیش بہا اضافہ کیالیکن جب انگریزوں نے ہندوستان پر اپنا قبضہ جما دیا تو انگریز جلد ہی جان گئے کہ اس ملک میں اگر کوئی زبان مشترکہ زبان بننے کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ اردو ہے، اس لئے انگریز وں نے فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں اردو کی ابتدائی تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس کی بدولت اردو زبان کو ترقی و ترویج ملی مگر انگریزی اقتدار کے زیر سایہ 1867ء میں چند ہندوتنظیموں اور لیڈروں نے اردو زبان کی مخالفت شروع کر دی۔ اس کااردو زبان کے سفر اور اس کی ترقی پر کافی منفی اثر پڑا، بالخصوص اردو ہندی تنازعہ شروع ہوا۔ 1867ء میں بنارس کے بڑے بڑے ہندو رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ سرکاری عدالتوں اور دفاتر میں فارسی اور اردو کو یکسر ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ ہندی کوسرکاری زبان کے طور پر رائج کیا جائے۔ ہندوؤں نے برطانوی حمایت کے بل بوتے پر سب سے پہلا حملہ اردو زبان پر کیا اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر ایک اردومخالف تحریک شروع کی۔اس کے زیراثر اردو زبان سے عربی اور فارسی لفظیات کو نکال باہر کر کے اس میں سنسکرت الفاظ شامل کرکے ہندوستانی کے نام سے ایک نئی زبان بنادالی۔ان لوگوں نے کہا کہ اردو قرآن کے رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اس کی جگہ ہندی یادیوناگری رسم الخط جاری کیا جائے ۔ الہٰ آباد کو لسانی تعصب کی اس تحریک کا صدر دفتر بنایا گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ متعصب ہندوؤں نے مختلف ریاستوں میں ورکنگ کمیٹیاں تشکیل دیں تاکہ تمام ہندو کو اس تحریک میں شامل کیا جاسکے ۔ سرسید احمد خان نے ہندوستان کے بنارس شہر میں واضح الفاظ میں پیش گوئی کی تھی کہ اگرہم وطنوں کی تنگ نظری اور تعصب کا یہی عالم رہا تو وہ دن دور نہیں جب ہندوستان ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایک علیحدہ زبان کے طور پر ہندی کی تشکیل کے سیاسی لائحہ عمل سے قبل "ہندی " اردو ہی کا پرانا نام تھا۔ فطری طور پر فارسی کا اقتدار ہونے کے سبب مسلم دور اقتدار کے اکثر متون فارسی رسم الخط میں ہیں اور ایسا اس لئے بھی ہے کہ فارسی رسم الخط کو اختیار کرنے کی آزادی ہر فرد کو حاصل تھی،جب کہ سنسکرت اور دیو ناگری لپی پر برہمن طبقہ کی اجارہ داری تھی اور عام ہندو اس میں مداخلت کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔اس لسانی تعصب نے چلتے چلتے بعد میں "ہندی، ہندو، ہندوستان " جیسے فرقہ وارانہ نعرے کی شکل اختیار کر لی۔ ہندوستان کے ہندو لوگوں نے دیو ناگری رسم الخط کی شکل میں اسی نئی زبان کو تقویت دینے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی جس کے نتیجے میں اردو چشم زدن میں محض اقلیتی مسلم طبقے کی زبان بن کر رہ گئی۔ اس وجہ سے دو قومی نظریے کی باقاعدہ بنیاد پڑناشروع ہوئی جو 1947ء میں برصغیر کی خون آشام تقسیم پر منتج ہو ئی۔ جب پہلے پہل اردو زبان کی مخالفت شروع کی گئی تو ہندوستان میں رہنے والے مسلمان، دانشور، اور ادیب جس میں خاص کر سرسید احمد خان اور علی گڑھ تحریک کے اکابرین شامل تھے، وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور انہیں ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں اپنے ٹھوس خیالات تک میں ردوبدل کر نا پڑی۔ اس موقعے پر آپ نے فرمایا تھا:"مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب ہندو اور مسلمان بطور ایک قوم کے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے "
ہندوستان میں اردو زبان کی فرقہ وارانہ مخالفت چہارسو شروع ہوئی تو سرسید احمد خان نے تحفظ اردوکے لئے بہت سارے اقدامات کر نے کا ارادہ کیا۔ 1867ء میں انہوں نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ ایک "دارالترجمہ " قائم کیا جائے تاکہ یونیورسٹی کے طلبا کے لئے کتابوں کا اردو ترجمہ کیا جا سکے۔ جونہی یہ خبر اردو مخالف لوگوں تک پہنچ گئی تو وہ برہم ہوگئے اور اس مطالبے کو شدت سے مخالفت کی۔ سرسید جیسی روشن خیال شخصیت نے اردو کی تحفظ کے لئے ہندوؤں کا خوب عاقلانہ مقابلہ کیا اور الہٰ آباد میں ایک تنظیم سنٹرل ایسوسی ایشن قائم کی اور سائنٹفک سوسائٹی کے ذریعے اردو کی حفاظت کا بیڑہ اٹھایا۔ بہرصورت یہ لسانی تقسیم کا مسئلہ انیسویں صدی کی چوتھی دہائی سے سر اٹھا رہا تھاجب شمال مغربی صوبوں میں سرکاری کام کاج کی زبان کے طور پر اردو کے رواج کے فوراً ہندو تعلیم یافتہ اعلیٰ طبقے نے اس پر احتجاج کیا اور اگست 1840ء میں جب حکومت نے آسان اور سہل زبان استعمال کرنے کی ہدایت متعلقہ محکموں کو دی اور 1856ء میں محکمہ مال کے جونیر افسران کو دیو ناگری رسم الخط میں لکھنے کی ہدایت دی گئی۔ یہاں سے شعبہ مال گزاری میں ہندی کو داخلہ ملا۔ اس چیزکو مدنظر رکھتے ہوئے سرسید نے وائسرائے اور گورنر جنرل کو یکم اگست 1867ء کو ایک میمورنڈم (یاداشت) پیش کی جس میں وقت کے نظام تعلیم کو ناقص بنایا گیا، جس کی بنیاد انگریزی ذریعہ تعلیم پر تھی۔ سرسید کے خیال میں "یورپین علوم وفنون اور سائنس کی روشنی " کو عام کیا جانا ضروری تھا ۔اس لئے انگریزی نہیں بلکہ دیسی زبان موزوں تھی۔ اس میمورنڈم پر دس افراد کے دستخط تھے جن میں چار یعنی اسر چند مکر جی، راجا جے کشن داس، منولال اور بدری پرساد جیسے وسیع النظر غیر مسلم تھے۔ اس منصوبے کو برطانوی حکومت نے رد کر دیا، جس کی اطلاع 5 ؍ستمبر 1867ء کو بیلی نے برٹش انڈین ایسوسی ایشن کے صدر اور اراکین کو ایک خط کے ذریعے دی۔اس تجویز کو حکومت نے اگرچہ ردکردیا لیکن اس نے کلکتہ یونیورسٹی، بنارس انسی ٹیوٹ کے سکریٹری اور دوسرے کئی افراد سے اس بارے میں اپنی رائے بھی مانگی۔ بعد میں 1868ء میں بنارس انسی ٹیوٹ کا ایک خصوصی اجلاس طلب کیا گیا جس میں خود سرسید احمد خان اور بابو شوپرساد بھی شریک تھے۔ اس اجلاس میں بابو شوپرساد نے کچھ بولنے سے انکار کیا اور بالکل خاموشی اختیار کی ۔ اس کی خاموشی دیکھ کر صدر نے محسوس کیا کہ اس موضوع پر کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہتا اور اجلاس کو برخاست کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے بھی اپنی کتاب "ہندی اردو تنازعہ " میں سرسید کے یکم اگست 1867ء کے یاداشت کا ذکر کر تے ہوئے لکھا :" اس درخواست پر حکومت نے خاص توجہ دی تھی لیکن بعض دوسری باتوں کے ساتھ بڑی رکاوٹ یہ پیدا ہوگئی کہ بنارس کے ہندووں کی طرف سے اس کی مخالفت شروع ہوگئی۔ اردو کے مخالفین نے اخبارات میں اس کا مطالبہ کر دیا کہ اس مجوزہ یونیورسٹی میں مسلمانوں کے لئے اردو زبان اور ہندوؤں کے لئے ہندی زبان مخصوص کی جائے "۔ آخر کار ہندوؤں نے اردو زبان کی سخت مخالفت کی اور ہندی زبان کو درجہ دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے، اس لئے انہوں نے اردو کے بجائے ہندی زبان کی طرف توجہ دی لیکن اس کے باوجود سرسید احمد خان نے اردو زبان کی حمایت جاری رکھتے ہوئے اردو دوست کام جاری رکھا۔ ان کے بعد ان کے لائق جانشینوں نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک نے یہ لسانی خدمت بحسن وخوبی انجام دی۔آج اگر ہندوستان میں اردو بولی اور لکھی سمجھی جاتی ہے تو اس کا سہرا سرسید احمد خان کو باھندنا چاہیے۔