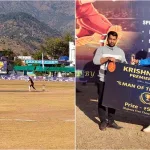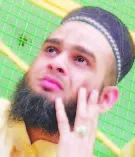ادبی تنقید کے سلسلے میں یہ بات اپنی جگہ نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ صحت مند تنقید کسی ادیب کو خوب سے خوب تر کی جستجو میں سرگرم عمل رکھتی ہے۔صحت مند تنقید کی خوبی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ ادب کی ماہیت؛تحلیل وتجزیہ؛حقیقت کے ادراک اور ادب پارے کی خوبیوں اور خامیوں کو لاگ لگاو ، طرفداری اور ذاتی اغراض و مقاصد کے جذ بے سے بلند ہوکر تعین قدر ومقام کو متعین کرتی ہے۔ سماجی ؛تاریخی اور تہذ یبی بدلاو کے ساتھ ساتھ ادب میں بھی تغیر پزیری کا عمل کارفر ما رہا ہے۔اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ادب کی پرکھ اور افہام وتفہیم کے معیاربھی بدلتے رہے ہیں۔کبھی کسی ادب پارے میں خارجی محاسن ومعائب تلاش کیے گئے اور کبھی ادبی فن پارے کی زیریں لہروں کی چھان بین پہ توجہ مبذول کی گئی۔ادب چونکہ زندگی کاآئینہ ہوتا ہے اس لیے کچھ اس کا تعلق انسانی جبلتوں اور نفسیاتی خواہشوں سے جوڑتے ہیں۔اہل نقد کا دوسرا گروہ ادب کے تانے بانے معاشی؛سیاسی اور سماجی حالات سے جوڑتا ہے۔بہر حال قدیم وجدید اصول ونظریات کی کشمکش اور متضاد پہلو ساتھ ساتھ اپنا عمل اورردعمل جاری رکھتے ہیں۔یقین کیجئے کہ انہی مثبت ومنفی پہلوؤں کے تحت قوت نقد وانتقاد کو فروغ حاصل ہوا ہے۔بنیادی طور پر ادبی تنقید کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ایک نظریاتی تنقید اور دوسرا عملی تنقید۔جہاں تک نظریاتی تنقید کا تعلق ہے یہ نظریاتی اصولوں سے بحث کرتی ہے جب کہ عملی تنقید اصولوں کے پیش نظر تخلیقی فن پارے کو جانچتی پرکھتی ہے۔
بیسویں صدی کے انسان نے حہاں سائنسی؛تکنیکی ؛سماجی ؛سیاسی ؛تہذ یبی وثقافتی میدان میں حیرت انگیز ترقی کی تو وہیں علمی وادبی تحریکات؛رجحانات وفکریات اور نظریات کے میدان میں حیات وکائنات سے متعلق کچھ ایسے انکشافات کیے جو ادب وسماج کو ایک نئے تناظر میں سمھنے اور سمجھانے میں معاون ثابت ہوئے ہیں۔اس سلسلے میں ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگانوی کا بیان نہایت معلوماتی اور بصیرت افروز معلوم ہوتا ہے وہ ایک جگہ رقمطراز ہیں:
"بیسویں صدی نے اردو کو جمالیاتی تنقید؛تاثراتی تنقید؛نفسیاتی تنقید؛کلاسیکی تنقید؛تقابلی اور تجزیاتی تنقید؛رومانی تنقید؛سماجی یا عمرانی تنقید؛سائنٹیفک تنقید اور جدید تنقید کا ذریعہ اظہار دیا جس سے تاریخی اور عصری مواد کی بنیاد سامنے آئی اور عہد کے معاشرتی اور فکری حالات کا زائدہ سامنے آیا۔یہ صحیح ہے کہ زندگی اور اس کی بیکراں وسعت ادب کا موضوع ہے۔اس طرح تنقید کا تعلق بالواسطہ زندگی سے بھی ہے۔حیات انسانی اورادب سے متعلق جتنے افکار اور نظریات ہوسکتے ہیں؛تنقید انھیں سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔
عالمی تنقید کا دوسرا خیمہ اسلوبیاتی تنقید؛اسطوری تنقید؛ وجودی تنقید؛مظہری تنقید؛ساختیاتی تنقید؛پس ساختیاتی تنقید؛مابعد جدید تنقید اور آرکی ٹائیپل تنقید پر زور دیتا رہا ہے۔تنقید کے ان دبستانوں میں آرکی ٹائیپل؛ساختیاتی؛پس ساختیاتی اور مابعد جدید تنقید کی دستک اردو میں اکیسویں صدی کے لیے تھی۔ امتزاجی تنقید اور تخلیقیت پسندتنقید بھی اسی شمار میں ہے۔"
(اکیسویں صدی میں اردو تنقید؛مشمولہ۔"تنقید وتفہیم"مناظر عاشق ہرگانوی؛ ایجوکیشنل پبلشنگ ہاوس دہلی2014 ص18)
تنقید کے ان تمام دبستانوں یا مکتبہ ہائے فکر نے بلاشہ ادبی تنقید کو نئی جہات وآفاق کی صورت میں وسعت دی ہے۔اکیسویں صدی میں اس بات کی توقع کی جاسکتی ہے کہ اردو میں ساختیاتی تنقید وسعت اور گہرائی کے نئے ابعاد سامنے لائے گی۔چونکہ اس میں لکھاری؛شعریات اور قاری تینوں ایک اکائی تشکیل دیتے ہیں۔معاصر تنقید کا نیا و ژ ن تھیوری یعنی نظریہ سازی پر ہے۔دراصل انسانی فکر اکیسویں صدی میں پہنچتے پہنچتے بالکل ایک نیا رنگ روپ اختیار کرچکی ہے اور انسانی موضوعات وتصور ذات سے متعلق ایسے ایسے سوالات سامنے آئے ہیں کہ ان سے صرف نظر کرنا ناممکن نہیں ہے۔ساختیات؛پس ساختیات؛قاری اساس تنقید؛تشکیل ؛ رد تشکیل اور مشرقی شعریات جیسے تمام تنقیدی نظریے ذہنی وسعتوں اور نئے تنقیدی منظرنامے کا پتا دیتے ہیں۔ساختیات لسانی اصول وضع کرنے کے ساتھ ساتھ اس امر پر زور دیتی ہے کہ قاری یا سامع تحریر کی قرات ؛الفاظ کی ادائیگی یا تحلیل سے بہت سے معانی اخذ کرسکتا ہے۔اسی لیے روائتی نظریہء ادب اور تنقیدی رویوں کو اس نے تشت ازبام کیا ہے۔پس ساختیاتی تنقید ؛ساخت شکن تنقید؛ امتزاجی تنقید؛مابعد جدید تنقیداور تخلیقیت پسند تنقید میں تخلیقی عمل کی نفسیات ؛تہذ یبی وثقافتی سرچشمے؛نسلی؛کائناتی اثرات ؛لوک روائیتوں؛اجتماعی لا شعور کے محرکات ؛انسانی جڑوں کی تلاش؛دیومالا؛تصوف؛ویدانت اور جمالیات واخلاقیات سے مملو ہے۔چناں چہ اکیسویں صدی میں مذ کورہ بالا نئے تنقیدی نظریات کی عمل آوری نے کسی حدتک اردو تنقید کو خاصی وسعت اور پیش رفت کی راہ پہ گامزن کیا ہے۔
جہاں تک ریاست جموں وکشمیر میں اردو تنقید کی پیش رفت کا تعلق ہے اس حوالے سے یہاں پہلے کے مقابلے میں اردو تنقید کی موجودہ صورت بہت حدتک غیر تسلی بخش ہے۔البتہ چند اہل نقد ایسے ہیں جنھوں نے تنقید میں اپنی محنت ولگن سے ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل کیا ہے۔ دراصل تنقید ایک غیر جانبدارانہ عمل ہے اور اس میں میانہ روی کاپاس ولحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ انسان کی سرشت میں چونکہ خیر وشر کا مادہ فطری طور پر موجود رہتا ہے۔ اس لیے کسی تخلیقی یا غیر تخلیقی ادب پارے میں جہاں خوبیاں ہوتی ہیں تو وہیں کچھ خامیاں بھی ہوسکتی ہیں۔ ایک بہترین نقاد؛تنقید کے نام پہ نہ تو گوشت کوٹتا ہے اور نہ بے جا تعریفوں کے پل باندھتا ہے۔بلکہ وہ تو اپنے وسیع مطالعے ومشاہدے کی بنیاد پہ منطقی واستدلالی انداز میں کسی ادب پارے کے محاسن ومعائب کی نشاندہی کرتا چلا جاتا ہے۔میرے خیال میں دو طرح کے شخص علم وآگہی سے محروم رہتے ہیں۔ایک مغرور اور دوسرا شرمیلے مزاج کا آدمی۔تنقید نگار جب مصلحت پسندی اور جانبد اری کے جذ بے سے دور رہ کر کام کرے گا تو لقینا" وہ ادیب اور ادب پارے کے ساتھ انصاف کرے گا۔یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ عصری معاشرے کے آدمی میں سچ سننے ؛بولنے اور سچ دیکھنے کا مزاج نہیں رہا۔یہی وجہ ہے کہ اکیسویں صدی میں ملکی سطح پہ تقریبا"دو درجن کے قریب انتقادیات کے میدان میں ایسے نام ابھرکر سامنے آتے ہیں جنھوں نے اردو تنقید کواعتبار؛معیار اور وقار بخشا ہے۔ ریاست جموں وکشمیر کی یہ خوش نصیبی رہی ہے کہ یہ شروع ہی سے قدرتی نظاروں اور دلکش وادیوں کی وجہ سے بیرون ریاست کے دانشورں ؛سیاحوں ؛ فنکاروں؛ مفکروں ؛ عالموں؛فاضلوں اور ادیبوں و شاعروں کی دلچسپی کی آماجگاہ رہی ہے۔یہاں تک کہ کچھ علمی و ادبی ہستیوں کو یہاں کی دا نش گاہوں میں ایک طویل عرصے تک اپنی علمی وادبی ذہانت ؛ ذکاوت اور فہم وفراست کے چراغ جلانے کا موقع بھی ملا۔مثلاً پروفیسر گیان چند جین؛پروفیسر جگن ناتھ آزاد؛پروفیسر منظر اعظمی؛پروفیسر شیام لال کالرا؛پروفیسر آل احمد سرور؛پروفیسر محی الدین قادری زور؛پروفیسر شکیل الرحمن اور مظہر اما م وغیرہم ؛یہ اردو کی وہ مایہ ناز ہستیاں تھیں جن کا آبائی تعلق ہندوستان کے مختلف شہروں سے تھا لیکن انھوں نے جموں وکشمیر کی علمی وادبی دانش گاہوں میں ایک طویل عرصہ گزرا اور اردو تحقیق وتنقید کو فروغ دیا۔
اکیسویں صدی میں اردو تنقید کی پیش رفت کے حوا لے سے ریاست جموں وکشمیر میں جن تنقید نگاروں نے اپنی تنقیدی صلا حیتوں سے تنقید کو وقار بخشا ہے ان میں پروفیسر حامدی کاشمیری؛ پروفیسر ظہور الدین؛ محمد یوسف ٹینگ ؛غلام نبی خیال اور پروفیسر قدوس جاوید شامل ہیں۔ان تنقید نگاروں نے تنقیدی اصول ونظریات کو عملی طور پر برتا ہے اور ادب؛ادیب اور ادبیت کی صراحت ووضاحت میں استدلالی اور منطقی اسلوب اختیار کیا ہے۔حامدی کاشمیری کا شمار بلند پایہ نقادوں میں ہوتا ہے۔"جدید اردو نظم پر یورپی اثرات" سے لے کر" اکتشافی تنقید کی شعریات" تک ان کا طویل تنقیدی سفر نہایت معتبر اور تازہ کاری سے تعلق رکھتا ہے۔حامدی کاشمیری کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ اکتشافی تنقید کے بنیاد گزار و علمبردار ہیں۔پروفیسر قدوس جاوید نے حامدی کاشمیری کی جدید تنقیدی تھیوری کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہے:
"حامدی کاشمیری نے جدید ترین لسانی؛ادبی اور ثقافتی تھیوریز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اردو شعر وادب کی تفہیم وتعبیر کی جو کوششیں کی ہیں اس کا اعتراف ہر شخص کرتا ہے۔لہذا یہاں صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ حامدی کاشمیری نے تنقید کے حوالے سے شعر کا آزاد وخود مختار وجود؛متن سے مصنف کے غیاب؛متن کی قرات کے تفاعل میں قاری کی شرکت؛شعر میں الفاظ کا غیر روائتی برتاو؛ تخلیق کی تفہیم میں زبان کا کردار اور متن میں معنی کی کھو ج تخیلی تجربہ کی موجودگی وغیرہ حامدی کاشمیری کی تنقید نگاری کے بنیادی امتیازات ہیں"
(1۔"شیرازہ اردو—-ایک رسالہ؛ایک تحریک"مشمولہ۔شیرازہ گولڈنجوبلی نمبر۔جموں وکشمیر کلچر اکیڈمی۔2013ص43)
حامدی کاشمیری کے اکتشافی نظریہء نقد پر اگرچہ شروع شروع میں ادبی حلقوں میں کافی بحث وتمحیص ہوئی اور کئی سوال اٹھائے گئے لیکن حامدی کاشمیری نے اپنے نظریہء نقد کی افہام و تفہیم کے لیے با ضابطہ ایک تھیوری پیش کی ؛جس کے تحت انھوں نے یہ ثابت کردیا کہ ادب پارہ یا تخلیقی فن پارے کو جانچنے پرکھنے اور اسکے تعین قدر میں صرف موضوعیت و الفاظ کے معانی اخذ کر نے تک محدود رکھنا کار احمقانہ ہے۔وہ تجربہ؛ متن کی قرات اور تخیلی جہان کو بہت حد تک اہم قرار دیتے ہیں۔گویا حامدی کاشمیری کے اکتشافی نظریے کا براہ راست تعلق ادیب کے ذاتی تجربے کے کشاف سے ہے۔ بیسویں صدی کی اخری اور اکیسویں صدی کی پہلی دہائی کے دورانیہ میں حامدی کاشمیری کی جو انتقادی کتب منظرعام پر آئیں ان میں"کارگہہ شیشہ گری"(2003)"اکتشاف بطور تنقید"(2003)"متن میں معنی کا عمل"(2006)"غالب جہان دیگر"(2009)اور"اردو افسانہ—-تجزیہ"(2010) نہایت اہم اور قابل مطالعہ ہیں۔
ڈاکٹر ظہورالدین اردو فکشن کی تنقید کا ایک معتبر نام ہے۔ان کے تحقیقی مقالے"بیسویں صدی کے اردو ادب میں انگریزی کے ادبی رجحانات" ان کی تحقیقی وتنقیدی بصیرت کا ایک قابل قدر کارنامہ ہے۔وہ عملی تنقید کے قائل ہیں اور ایک ایسے نقاد ہیں جو تنقیدی اصول و نظریات کے تناظر میں کسی ادب پارے کو جانچتے پرکھتے ہیں۔ وہ ادیب سے زیادہ ادب پارے کو اہمیت دیتے ہیں۔شخصی مرعوبیت کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔اسی لیے وہ دوران تنقید کسی فن پارے میں در آئے محاسن ومعائب کی نشاندہی استدلالی انداز میں کرتے چلے جاتے ہیں۔پروفیسر ظہورالدین کی تنقید نگاری کا ایک نمایاں وصف یہ ہے کہ وہ معائب کی صراحت وضاحت کے دوران ادبی رویے اور اسلوب کا خاص خیال رکھتے ہیں۔اس سلسلے میں ان کی یہ شعوری کوشش رہتی ہے کہ قلمکار کا دل نہ ٹوٹے۔ "کہانی کا ارتقا"اور"جدید ادبی وتنقیدی نظریات" پروفیسر ظہور الدین کی ایسی تنقیدی کتابیں ہیں جو ان کے تنقیدی شعور و بصیرت کی غماز ہیں۔
محمد یوسف ٹینگ نقاد سے ز یادہ محقق ہیں۔ان کے مضامین تاریخی؛تہذ یبی وثقافتی نوعیت کے ہوتے ہیں اور کشمیریات سے ان کی دلچسپی کا پتا دیتے ہیں۔زبان وادب کے محقق ونقاد ہونے کی حیثیت سے محمد یوسف ٹینگ ایک منفرد مقام پر فائز ہیں۔یہ امتیازی وصف انہیں علم وآگہی کے جنون کے باعث حاصل ہوا ہے۔ان کے تنقیدی مضامین میں"منٹو کی افسانہ نگاری"اقبال—-شعر اور خطابت"مہجور کا جمالیاتی شعور"ابوالکلام آزاد کی ادبی شخصیت" خصوصیت کے حامل ہیں۔محمد یوسف ٹینگ ایک مخصوص صاحب طرز انشا پرداز بھی ہیں۔غلام نبی خیال ایک ہمہ جہت ادبی شخصیت ہیں۔ انھیں انگریزی؛اردو ؛ فارسی اور کشمیری زبان پر خاصا عبور حاصل ہے۔ایک بے باک اور بے لاگ نقاد کی حیثیت سے ادبی حلقوں میں معروف ہیں۔ان کے سینکڑوں تنقیدی وتحقیقی مضامین اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ وہ نہایت محنت ولگن سے ادب کے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ شخصیت پرستی؛مصلحت پسندی اور سود و زیاں کا خیال نہ کرتے ہوئے خالص تنقید لکھتے ہیں۔ اچھا کیا ہے ؛برا کیا ہے۔سچ کیا ہے اور جھو ٹ کیا ہے۔ایک اچھے نقاد میں یہ مستحسن جذ بہ ہونا چاہیئے۔غلام نبی خیال میں یہ جذبہ بدرجہ اتم موجود ہے۔تنقید سے متعلق اپنے نظریے کا اظہار کرتے ہوئے وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:
"جب بھی کوئی تنقیدی مضمون ہماری نظروں سے گزرتا ہے تو ہمیں اس کے ابتدائی حصے سے ہی معلوم پڑتا ہے کہ اس میں ایک خاص طرح کے پہلے ہی سے طے شدہ نقطئہ نظر سے کام لیاگیا ہے۔جس کے مارے اس کی افادیت اور صحت پر کاری ضرب پڑ چکی ہے۔کشمیر میں ادبی تنقید صرف اسی صورت میں پنپنے کی درخور کہلائی جاسکتی ہے جب نقاد ذاتی پسند ناپسند اور انفرادی فکر و خیال کی مصلحتوں سے خود کو بالا کرکے اس صنف ادب کے ساتھ انصاف کرکے نہ صرف اپنی ایمانداری کا ثبوت پیش کرے بلکہ تنقید کی دنیا میں بھی نام پیدا کرسکے"
(2۔مشمولہ۔"ہمارا ادب"(تنقید نمبر)جموں وکشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز؛2014 ؛ص432)
اکیسویں صدی کی پہلی اور دوسری نصف دہائی کے دوران غلام نبی خیال کی چند اہم تنقیدی کتایبں منظر عام پر آئیں کہ جنھوں نے اردو ادبی حلقوں میں خاصی شہرت ومقبولیت حاصل کی اور تنقیدی شعور وبصیرت کے نئے باب کھولے۔مثلا" فکر خیال"(2007)"خیالات"(2009)اور "خیال قلم"(2012)ان کی تنقیدی نگارشات کی عمدہ مثالیں ہیں۔
پروفیسر قدوس جاوید کا مطالعہ وسیع اور مشاہدہ گہرا ہے۔ ادب پڑھنا اور لکھنا انھوں نے اپنا نصب العین بنالیا ہے۔یہی وجہ ہے کہ اردو ادبی رسائل وجرائد اور اخبارات میں ان کی تحریریں اکثر چھپتی رہتی ہیں۔زبان وبیان پہ انھیں خاصا عبور حاصل ہے۔جس کی وجہ سے ان کی تحریریں کافی معلوماتی اور دلگرفتہ ہوتی ہیں۔ ترقی پسند تحریک؛جدیدیت اور مابعد جدیدیت کی تھیوری کے نباض ہیں۔چناں چہ ان تمام تحریکات و رجحانات کی افہام وتفہیم میں ان کی دلچسپی کا قائل ہونا پڑتا ہے۔قدوس جاوید کی تنقید نگاری کے جوہر ہمیں ان کی تنقیدی کتب"ادب کی سماجیات" اقبال کی جمالیات"(2000) "اقبال کی تخلیقیت"(2005)"متن؛معنی اور تھیوری"(2015)"غلام رسول نازکی—-ایک لیجینڈ"(2016)اور"اقبال اور مابعد جدید شعریات"(2016) میں کھلتے نظر آتے ہیں۔
آخر پر اس بات کا ذکر کرنا لازمی ہے کہ میرا تجربہ اور مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ دراصل صحت مند تنقید مصنف اور تصنیف کے درمیان نہ صرف روشن امکانات پیدا کرتی ہے بلکہ خوب سے خوب تر کی جستجو کی راہ پہ گامزن کرتی ہے۔یہ حقیقت ہے کہ خیر وشر کا مادہ انسان میں فطری طور پر موجود ہوتا ہے۔البتہ ایک اچھے تنقید نگار کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ ذاتیات اور تعلقات سے دور رہ کر بڑے شائستہ اور عالمانہ انداز میں کسی ادب پارے کا اس طرح تنقیدی جائزہ لے کہ اس کے معائب ومحاسن بڑی صراحت ووضاحت کے ساتھ قاری کے سامنے آجائیں۔
رابطہ :اسسٹنٹ پروفیسر شعبئہ اردو بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری(جموں وکشمیر)
فون نمبر9419336120